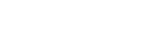کہانی کی کہانی
یہ جدید تکنیک میں بیان کی گئی ایک جدید کہانی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار سندیپن کولے، جس کی پیدائش فورسیپس کی مدد سے ہوئی تھی، کہانی کے مصنف صدیق عالم سے نالاں ہے جو اپنی کہانی اپنے ڈھنگ سے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات اسے پسند نہیں۔ وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتا ہے۔ وہ بار بار مصنف سے قلم چھین لیتا ہے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود اس کی زندگی اسی لیک پر چل پڑتی ہے جس پر اس کا مصنف اسے چلانا چاہتا ہے۔ آخرکار وہ مصنف سے ٹکر لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایک ایسے نہج پر چل پڑتا ہے جو اس کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ کہانی کے اختتام سے قبل مصنف اس سے کہتا ہےکہ تم نے سوچا تھا کہ تم صفحات سے باہر بھی سانس لے سکتے ہو، دیکھو، تم نے اپنا ستیاناس کر لیا نا؟
بالی گنج روڈ پر ایک شخص سیاہ کارڈیگن پہنے تنہا کھڑا بس کا انتظار کر رہا ہے۔ تین ماہ قبل اس نے اپنی پرانی تین منزلہ عمارت سے کو د کر خود کشی کرنے کی کوشش کی تھی اور نیچے سڑک پر معلق بجلی کے تار کے سبب ناکام رہا تھا جس نے اسے نیچے فٹ پاتھ سے بارہ فیٹ اوپر روک لیا تھا۔ تار سے نیچے گر کر اس کا ایک ہاتھ اور دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ سرکاری اسپتال میں دو ماہ زیر علاج رہا۔ مگر اس حادثے کے بعد ایک عجیب واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہ جس ذہنی تناؤ سے گزر رہا تھا اچانک وہ ختم ہو گیا ہے۔
سندیپن۔۔۔ ہاں، آپ مجھے سندیپن کولے کے نام سے بلا سکتے ہیں، سندیپن کولے اور یہاں سے میں اپنی کہانی خود سنانا چاہتا ہوں۔ یہ صدیق عالم، یہ ایک انتہائی بکواس قسم کا کہانی کار ہے، وہ سچ کو بھی کہانی بنا دیتا ہے اور کہانی کو سچ، جو اور بھی زیادہ برا ہے۔ وہ ہمارے ہی محلے میں ایک دوسری پرانی عمارت میں رہتا ہے جس کی سیڑھیاں ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہیں۔ وہ رات کے آخری پہر تک جاگتا ہے اور دن سے اسے نفرت ہے۔ وہ مذہب کو قدیم قبائلی جنگ کی صورت میں دیکھتا ہے جس کے خد و خال اکیسویں صدی میں زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں، قومیت کے تصور کو ایک غیرفطری جوہر سے عبارت کرتا ہے، ہندوستان کی آزادی کو ایک مِتھ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، وہ مغربی کلاسیکی موسیقی کا دیوانہ ہے، ہمیشہ تنہا رہنا چاہتا ہے مگر ایک شہر خبرا کی طرح شہر کی سڑکوں پر گھومتا رہتا ہے، وہ لفظوں میں یقین نہیں رکھتا، انھیں انسان کی ملمع کاری سمجھتا ہے، ادبی محفلوں سے گھبراتا ہے اوراس کی نظر میں انسان خدا کا لکھا ہوا سب سے بےتکا ڈراما ہے جس کے سارے کردار یا تو بری طرح کنفیوزڈ ہیں یا ایک احمقانہ یقین سے سرشار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی مقدس نہیں ہے۔ ایسے انسان کا بھروسا نہیں کیا جا سکتا۔ جانے وہ مدیر کیسے ہوں گے جو اس کی کہانیاں شائع کرتے ہیں اور وہ قاری، میں انھیں سمجھنے سے قاصر ہوں، جو اس کی کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ شاید اس کرۂ ارض پر، اس خدا کی بنائی ہوئی زمین پر، اس خاک آباد پر انسان کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو ہر طرح کے لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نظر آئےگی۔ ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے خیالات، ہر طرح کا عقیدہ، ہر طرح کا نظریہ، اب اس سیّارے پر سب کچھ ممکن ہے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگوں کی بھی اچھی خاصی تعداد آپ کو مل جائےگی جنہوں نے اپنی ماں کی کوکھ سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا تھا اور انھیں چمٹے سے پکڑ کر باہر لانا پڑا۔ ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میرے کان کے دونوں پردوں اور ہڈیوں پر اب بھی ان چمٹوں کا درد گاہے بگاہے جاگتا ہے۔ یہی نہیں، میں اپنا دایاں ہاتھ تیس ڈگری سے اوپر لے جا نے سے بھی معذور ہوں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ میرے سر کا درد بالکل نفسیاتی ہے اور میں چاہوں تو اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہوں گرچہ وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ اس جبری پیدائش کے سبب ہی میں اپنا دایاں ہاتھ اٹھا نہیں پاتا۔ اس تیس ڈگری کے بعدکا سارا کام میرا بایاں ہاتھ کرتا ہے 151 میرا پیارا، اکلوتا بایاں ہاتھ۔ میں نے اپنے سر کے درد کو سمجھنے کی بہت کوشش کی ہے، اپنے کالج کے ان ساتھیوں سے بھی مشورہ لیا ہے جو اب سرکاری اسپتال کے گندے گلیاروں میں بھٹکتے رہتے ہیں یا پرائیوٹ نرسنگ ہوم کی صاف ستھری راہداریوں میں اسٹیتھسکوپ اٹھائے گھومتے ہیں۔ میں نے نیشنل لائبریری میں بیٹھ کر کافی میڈیکل جرنل چھانے ہیں، سائبر کیفے میں بیٹھ کر دنیا بھر کی میڈیکل ویب سائٹس کو لاگ آن بھی کیا ہے۔
’’ڈاکٹر، کہیں یہ میرے بھیجے میں Serotonin کی کمی کے سبب تو نہیں؟‘‘ میں نے اپنے آخری ڈاکٹر سے کہا تھا۔ ’’ہو سکتا ہے میں اس کے سبب ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں جو درد کی شکل میں ظاہر ہو تا ہے۔‘‘
’’جہاں دھوپ میں کمی ہوتی ہے وہاں یہ کیمیا ئی اجزا بن نہیں پاتے، مثلا لنڈن، امسٹرڈم یا سان فرانسسکو،‘‘ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا۔ ’’مگرکلکتہ کا آسمان تو بالکل روشن ہے، بلکہ مجھے کہنے دیں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی روشن ہے۔‘‘
میں نے ایک بار اس ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جس نے یہ گھناؤنا کام کیا۔ کسی نے مجھے اس کا پتا نہیں بتا یا تھا مگر مجھے اس گندے سے نرسنگ ہوم کا علم تھا جہاں میں پیدا ہوا۔
اس نرسنگ ہوم میں صرف ایک ڈاکٹر بیٹھتی تھی اور اس میں صرف زچگی کے لیے ہی لوگ جاتے۔ مگر یہ سارا کام یہاں کی آیائیں انجام دیتیں جن کے چہرے ہر طرح کے جذبات سے عاری تھے۔ کلکتہ کے نچلے اور متوسط درجے کے تمام نرسنگ ہوم کی طرح اس نرسنگ ہوم میں بھی کوئی سندیافتہ نرس نہیں تھی، یہی آیائیں تھیں جو یونیفارم اور کیپ پہنے گھوما کرتیں۔ اس ڈاکٹر کے بال مہندی سے رنگے ہوے تھے اور سیندوری لکیر کی دونوں جانب اس کے سر کے گنجے پن کو پتلے پتلے گھنگریالے بالوں کے اندر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ جب میں نے اسے وہ تاریخ بتائی جب میں پیدا ہوا تو اس نے غیریقینی کی حالت میں سر ہلایا۔
’’اتنے پرانے رجسٹر تو اب کارپوریشن کے آفس میں ہی ملیں گے۔‘‘
’’آپ کو پورا یقین ہے وہ آپ نہیں تھیں؟‘‘
’’میں دو سال پہلے سرکاری اسپتال سے ریٹائر ہو کر اس میٹرنٹی ہوم میں آر ایم او کے طور پر آئی ہوں،‘‘ اس نے کہا۔
’’ویسے آپ اگر جھوٹ کہہ رہی ہیں تو اس کا آپ کو حق ہے،‘‘ میں کہتا ہوں۔ ’’کیا میں وہ چمٹا دیکھ سکتا ہوں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو دنیا میں لاتی ہیں؟‘‘
وہ تذبذب میں مبتلا ہے۔
’’شاید آپ کا مطلب ڈیلیوری فورسیپس سے ہے جو عمل جراحی میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر زچگی کے وقت۔‘‘
’’ہاں، ظاہر ہے میں کسی گھڑی ساز کی دکان پر تو ہوں نہیں۔ لیکن وہ ہے تو چمٹا ہی نا؟‘‘
’’شاید!‘‘ وہ ایک آیا کو بلاتی ہے جو بالکل پتلی دبلی بلکہ ہڈی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس نے غصے اور بیزاری سے میری طرف دیکھا ہے۔ وہ چمٹا لے آتی ہے جسے میں میز سے اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہوں۔ اس کے ٹھنڈے لوہے کو چھو تے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس چمٹے کے مقابلے میں اپنا سر کافی بڑا نظر آ تا ہے۔
’’بچوں کے سر پیدا ہوتے وقت اتنے بڑے نہیں ہوتے،‘‘ مجھے چمٹے کو اپنے سر پر آزماتے دیکھ کر آیا ٹوکتی ہے۔میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔
’’میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟‘‘ میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں۔
’’نہیں، یہ میٹرنٹی ہوم کی پراپرٹی ہے۔‘‘ شاید اس کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ وہ چمٹا واپس لے کر آیا کے حوالے کرتی ہے۔ ’’ویسے اگر آپ کو یہ فورسیپس چاہیے تو کالج اسٹریٹ میں کلکتہ میڈیکل کالج کے باہر کسی بھی میڈیکل ایکوئپمنٹ کی دکان پر مل جائےگا۔‘‘
’’دیکھا جائےگا،‘‘ میں کہتا ہوں۔ ’’میں ایک بار کسی بچے کو اس کے سہارے پیدا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرا فون نمبر نوٹ کریں گی؟‘‘
’’میرا خیال ہے یہ غیرضروری ہے،‘‘ ڈاکٹر نفی میں اپنا سر ہلاتی ہے، ’’مگر میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟‘‘
’’کیونکہ میں اس بچے کا ردعمل دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنی مرضی کے خلاف اس دنیا میں لایا جارہا ہو۔‘‘
’’کیا اس بچے کو جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کی مرضی کا پتا ہوتا ہے؟‘‘ وہ ایک آہ بھر کر شاید خود سے کہتی ہے۔پھر میری طرف تاکتی ہے۔ ’’صرف ایک صورت ہے اگر کوئی عورت اور اس کا شوہر اس کی تحریری منظوری دے۔ مگر یہ بھی میرے خیال میں ممکن نہیں۔ ہمیں بالکل ہی آخری وقت میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کیس نارمل ڈلیوری کا ہے، قیصری ہے یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں، چمٹے کا۔‘‘
’’اور یہ فیصلہ ہمیشہ کافی جلدی میں کیا جاتا ہوگا۔‘‘ میں مسکراتا ہوں۔ ’’کبھی جلد بازی میں، کبھی موٹی فیس کے لیے اور کبھی کنفیو زن کا شکار ہوکر اور اس پورے عرصے میں وہ بچہ آخری شے ہوتا ہوگا جس کی رائے کے بارے میں سوچا جائے۔‘‘
’’میرا خیال ہے ہم نے آپ کو کافی وقت دے دیا ہے۔ ایکسکیوز می، مجھے لیبر روم کی طرف جانا ہے۔‘‘
وہ گھنٹی بجاتی ہے اور میں نرسنگ ہوم کے پھاٹک سے باہر کا راستہ لیتا ہوں جہاں آسمان سفید ہے، سورج سوا نیزے پر ہے (آپ دیکھ رہے ہیں، صدیق عالم، وہ احمق کہانی کار، وقت کو کبھی اتنے اچھے ڈھنگ سے بیان نہ کر پاتا) اور ایک بس کی کھڑکی سے ایک عورت سر نکال کر صبح کا کھایا ہوا سارا کھانا ثابت و سالم قے کر رہی ہے۔ مجھے سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے اور میں سوچتا ہوں ایک دن میں اس گتھی کو سلجھا کر ہی رہوں گا کہ کیوں لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف پیدا ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے، اور جو کچھ ہوتا ہے اسے کہیں زیادہ انسانیت کے ساتھ، زیادہ جمہوری طریقے پر کیوں نہیں انجام دیا جاتا؟ کیا میڈیکل سائنس میں انسان کی مرضی کو کوئی دخل نہیں؟
آہ، دیکھیے، میرا سر اس جگہ پھر سے دکھنے لگا ہے جہاں مجھے اس دنیا میں لاتے وقت چمٹے کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ میرا جی چاہتا ہے میں اسے کسی دیوار پر دے ماروں۔
کارڈیگن کے اندر اسے پسینہ آ رہا ہے، مگر اسے پتا ہے کلکتہ میں جو چاروں طرف سے آبی گزرگاہوں ،ماہی گاہوں اور نمکین دلدلوں سے گھرا ہوا ہے، لوگ ہوا میں مرطوبیت کے سبب ٹھنڈ کو سمجھ نہیں پاتے اور اندر ہی اندر سردی کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ دراصل اسے کہیں نہیں جانا ہے اور اسے کسی خاص بس یا ٹرام کا انتظار بھی نہیں ہے، مگر عین ممکن ہے کہ وہ کسی بھی بس کے اندر بیٹھ کر کہیں بھی چلا جائے، یا تو دریا کی طرف بابو گھاٹ، یا بڑا بازار کی بھیڑ بھاڑ میں ستیہ نارائن پارک یا سیالدہ اسٹیشن جو ہر دس منٹ پر چھوٹنے والی لوکل ٹرین کے ذریعے اس عروس البلاد کو بنگال کی کھاڑی میں بکھرے ہوے دور دراز کے گاؤں دیہات سے جوڑتا ہے۔ یا پھر ممکن ہے وہ اگلے ہی بس اسٹاپ پر بس سے اتر کر اپنا گھر لوٹ آئے جہاں اس کی بیوی اس کے لیے سویٹر بن رہی ہے جسے تیار ہوتے ہوتے جاڑا ختم ہو چکا ہوگا اور اس کا بوڑھا پنشن یافتہ باپ جو پرانا شرابی ہے، بنگلہ کا اخبار دیکھ رہا ہے اور بالکنی سے باہر نظریں دوڑا رہا ہے جہاں دوسرے مکان کی چھتوں کے اوپر چیل اور کوے اڑ رہے ہیں۔ ایک بلّا بوڑھے کے سائے میں بیٹھا اس کے تھوکے ہوے مچھلی کے سر کی ہڈیوں اور کانٹو ں کو کھا کر اپنی مونچھیں پنجوں سے صاف کر رہا ہے۔
’’میں کھانا لگا دوں۔‘‘ اس کی بیوی اسے دیکھ کر آدھا بْنا ہوا سویٹر اور کروشئے رکھ دیتی ہے۔
’’کھانے میں کیا ہے؟‘‘
’’بھات، مچھلی، دال، چٹنی، کریلے۔‘‘
’’کریلے مجھے پسند ہیں۔‘‘ وہ سر ہلاتا ہے۔
بوڑھا اخبار سے سر اٹھا کر اس کی طرف دزدیدہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ ان دونوں کے لیے اسے ایک لمبے عرصے تک جینا ہوگا۔ عمارت سے کرایہ براے نام آتا ہے اور اب اس کی پنشن ہی ان دونوں کی زندگی کا آخری سہارا ہے۔ وہ آہ بھرتا ہے۔ شراب کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکار محصول پر محصول لگاتی جا رہی ہے۔ اس ملک میں ہمیشہ دقیانوسی خیالات کے لوگوں کی حکمرانی رہےگی جو محصول کے ذریعے لوگوں کو سدھارنے کے مہم میں لگے رہیں گے۔ ان سے زیادہ روشن خیال تو اس کی بہو ہے جو ہر رات شراب نوشی کے لیے آلویا مچھلی کے قتلے یا بیسن کے پکوڑے تل کر اس کے سامنے طشتری پر رکھ دیا کرتی ہے۔ یہ مشرقی پاکستان سے ہجرت کر کے آئے ہوے گھرانوں کی لڑکیاں کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہیں۔ وہ مچھلی کے فلس اور ہڈیوں نیز معمولی سے معمولی ساگ سبزیوں کے ڈنٹھلوں اور پتوں سے جنھیں اس ملک کی عورتیں عام طور پر پھینک دیا کرتی ہیں، لذیذ سے لذیذ کھانا بنا لیتی ہیں۔ بہو کے لیے اسے سندر بن جانا پڑا تھا جہاں مرد لکڑی اور شہد کی تلاش میں شیر، سانپ یا گھڑیال کا شکار ہو جایا کرتے ہیں اور عورتوں کے بیوہ بننے کی ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے۔ کہیں اس کے اندر یہ خوف قائم تھا کہ اس کا لڑکا زیادہ دن زندہ رہنے والا نہیں۔ گوسابہ کے جزیرے سے سبیتا جب بھٹ بھٹی پر، جو ایک گہرے نیلے آسمان کے نیچے گاڑھا سرخی مائل دھواں اڑاتی چلی جا رہی تھی، تین گھنٹے کے آبی سفر اور پھر ایک ڈھڈر سرکاری بس میں تین گھنٹے کے خشکی سفر کے بعد لائی گئی تو اسے کلکتہ پسند نہیں آیا۔ وہ اتنی بھیڑ بھاڑ کی عادی نہیں تھی۔ اس نے گوسابہ میں لوگوں کو ہر طرف اتنی شتابی سے بھاگتے ہوے بھی نہیں دیکھا تھا جیسے گھڑی کے کانٹے شہر کی سڑکوں پر گھومتے پہیوں کو دیکھ کر اچانک تیز ہو گئے ہوں۔ اس پر اس کے شوہر نے پھول سجّارات میں ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا جسمانی تعلق قائم کرنے سے معذور ہے، کہ وہ بچے کے سلسلے میں اس کی مرضی جانے بغیر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ گاؤں کے اسکول میں آٹھ کلاس تک پڑھی سبیتا الگ سونے کی عادی ہو چکی تھی۔ مگر اس کا دل کہتا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائےگا۔ یا پھروہ گوسابہ لوٹ جائےگی، جو اتنا برا نہیں۔
’’شٹ اپ!‘‘
آخری آواز میری تھی۔ آپ نے دیکھا، یہ صدیق عالم کس درجے کا قلمکار ہے! وہ آپ کی خواب گاہ کے اندر تک داخل ہونے سے نہیں چوکتا۔ اس کا قلم کب فحش نگاری پر اتر آئے خود اسے نہیں معلوم۔ اس کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے وہ شہر کے ہر حصے میں، ہر عمارت میں، ہر جھوپڑ پٹی میں، یہاں تک کہ طوائف کے محلوں، مسافر خانوں، کیل خانوں، اسپتال کے مردہ گھروں، بلکہ قبرستان اور شمشان گھاٹ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس لوگوں کی ذاتیات کے اندر جھانکنے کے ہر طرح کے ذرائع، ہر طرح کے آلے موجود ہیں اور جہاں یہ اینٹھے خان جھانک نہیں پاتا وہ اپنے تصورات کے ذریعے یا لوگوں کی نفسیات کا غلط یا صحیح مطالعہ کرکے ان کا خاکہ کھینچ ڈالتا ہے۔ ایک بار میں نے اسے ایک ٹرام کے اندر ایک تنہا سیٹ پر بیٹھے ایک کتاب پڑھتے پایا اور میرا یقین کریں، اس نے کتاب الٹی تھام رکھی تھی۔ شاید اس طرح وہ بھیڑ سے خود کو مستثنیٰ قرار دینا چاہتا تھا۔ مجھے ایسے لوگ نہیں بھاتے جو بھیڑ سے الگ جیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، انھیں جلد سے جلد تختہٗ دار تک پہنچانا لازمی ہو تا ہے، یا پھر ان پر نظر رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے لوگوں نے ہمیشہ نئی طرح کی مصیبتیں کھڑی کی ہیں، نئے نئے فرقے قائم کیے ہیں، انھیں ہر طرح کی چیزوں کو توڑنے کا جنون ہوتا ہے، ایک بچے کی طرح، یا ایک پاگل کی طرح یا ایک پیغمبر کی طرح جو پرانے عقائد کو توڑ کر ان کے ملبوں سے نئی عمارتیں تعمیر کرتا ہے۔
’’ٹکٹ!‘‘ کنڈکٹر کی آواز پر میں سر اٹھا کر دیکھتا ہوں۔
’’میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں،‘‘ میں کہتا ہوں۔
’’تو ٹرام سے اتر جائیے،‘‘ کنڈکٹر میرے ہی لہجے کی نقل کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں پر ایک دھندلی عینک پڑی ہے جو غلیظ ہو رہی ہے اور اس کی انگلیاں لانبی ہیں جن سے وہ ٹرام کے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں مسافر بھاری تعداد میں لٹکے ہوے ہیں۔ زیادہ تر وقت اسے مسافروں سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس ٹرام سے مسافر وں کی ایک بڑی تعداد کرایہ ادا کیے بغیر اتر جاتی ہے یا انھیں اترنا پڑتا ہے کیونکہ بھیڑ میں انھیں کنڈکٹر تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔
’’میں ٹکٹ کے پیسے دیتا ہوں،‘‘ مجھے صدیق عالم کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ دس روپے کا ایک نیا نوٹ نکال کر کنڈکٹر کی طرف بڑھا دیتا ہے۔
’’کہاں جانا ہے؟‘‘ کنڈکٹر نوٹ لے کر مجھ سے پوچھتا ہے۔ مگر میرے بتانے سے پہلے ہی صدیق عالم کہہ اٹھتا ہے،’’کالج اسٹریٹ!‘‘
وہ باقی کے پیسے لے کر ٹکٹ میری طرف بڑھا دیتا ہے اور کنڈکٹر کے آگے بڑھ جانے کے بعد اپنی کتاب کے درمیان انگلی دبا کر مجھ سے مخاطب ہوتا ہے۔ ’’تمھیں نہیں لگتا میں بھی اس کرۂ ارض پر آباد ہوں اور تمھارے آس پاس ہی جی رہا ہوں؟‘‘
آہ، تو اسے میرے خیالات کی آہٹ مل چکی ہے۔ شاید ان سے اسے سخت چوٹ پہنچی ہے۔ مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے۔ اس شخص کا رد عمل تو ایک عام انسان سے بھی گیا گزرا ہے۔
’’بھلے آدمی۔۔۔‘‘ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں۔ ’’میں تمھاری کہانیاں پڑھ چکا ہوں۔انھیں پڑھ کر کسی کا بھی بھلا نہیں ہو سکتا۔ شاید اب اس دنیا کو تم جیسے قلمکاروں کی ضرورت نہیں۔ تم سے زیادہ بہتر تو وہ لوگ ہیں جو چوراہوں پر بھیڑ لگا کر نقلی دوائیاں بیچتے ہیں، اس سے کم از کم کچھ لوگ تو زندگی کے بوجھ سے نجات پاتے ہیں۔‘‘
’’میں جانتا ہوں میں ایک اوسط درجے کی صلاحیت کا مالک ہوں۔ شاید میرے اندر وہ مہارت نہیں کہ لوگوں کی بھیڑ جما سکوں،‘‘ وہ کہتا ہے۔ ’’یہ لوگ جن کا تم ذکر کر رہے ہو، ایک ایک بار میں سو سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لیتے ہیں اور اپنی فصاحت کے بل پران میں سے پچیس فیصد لوگوں کو اپنی دوائیں بیچ ڈالتے ہیں۔جبکہ میرے جیسا قلمکار تو اپنی تین سو کاپیاں چھپوا کر ساری عمر اس کی دو سو کاپیاں تک بیچ نہیں پاتا۔‘‘
’’اس دنیا میں صرف وہی چیزیں بکتی ہیں جو لوگوں کا اچھا یا برا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں،‘‘ میں کہتا ہوں۔ ’’میرے عظیم قلمکار، تم تو کسی بھی لائق نہیں۔ اب اس سماج میں تمھاری حیثیت ایک appendix کی طرح ہے۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ ‘‘
مجھے پتا ہے میں نے اسے شدید چوٹ پہنچائی ہے۔ میں اس کا ازالہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اپنی کتاب کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور چلتی ٹرام سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اس عمر میں بھی اس کی پھرتی حیرت انگیز ہے۔ ہو سکتا ہے اور بھی لاکھوں احمقوں کی طرح اسے بھی لمبی عمر جینے کا جنون ہو۔ میرا خیال ہے یہ سماج کے لیے ایک بری خبر ہے۔
کالج اسٹریٹ میں کلکتہ یونیورسٹی کے پھاٹک کے باہر کافی بھیڑ ہے۔ پرانی کتاب کی دکانوں پر معمول کے مطابق دکاندار گاہکوں کو روک رہے ہیں، ان کی تھیلیاں کھینچ رہے ہیں۔
’’وکٹر ہیوگو!‘‘ ایک دکاندار میرا کندھا تھام کر کہتا ہے۔ ’’وکٹر ہیوگو، صرف پانچ روپے میں۔‘‘
’’وکٹر ہیوگو صرف پانچ روپے میں؟‘‘ میں حیرا نی سے کہتا ہوں۔ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو اپنے پرانی کتابوں کے کھوکھے کے باہر اپنے سر کے استخوانوں پر مفلر لپیٹے کھڑا ہے۔ میں اس کی بڑھائی ہوئی کتاب کو کھول کر دیکھتا ہوں۔ کیڑو ں نے اس کے اندر آر پار سرنگ بنا ڈالے ہیں۔ ’’Notre-Dame de Paris ‘‘کتاب کہتی ہے۔ اس کتاب کی جلد کبھی کافی خوبصورت رہی ہوگی، مگر اب بے رنگ اور داغدار ہو چکی ہے۔ اس کے صفحے پاپڑ کی طرح پیلے ہو رہے ہیں اور موڑنے پر ٹوٹ سکتے ہیں۔ شاید غلامی کے دنوں میں یہ انگلینڈ سے سمندر کا سفر طے کر کے ہندوستان آئی ہوگی۔ وکٹر ہیوگو صرف پانچ روپے میں! مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب پانچ ستارہ ہوٹلوں میں بیس بیس ہزار کے ڈنرکے اشتہار دیے جارہے ہوں، جب ملٹی پلیکس میں لوگ دو دو سو روپے کے ٹکٹ کے لیے فلموں کے لیے لائن لگاتے ہوں، جب فلم اسٹار اور کرکٹ کے کھلاڑی ایک ایک اشتہار کے لیے کروڑوں روپے لیتے ہوں، وکٹر ہیوگو صرف پانچ روپے میں، اور اس کے لیے بھی لوگوں کو کندھے سے پکڑ کر روکنا پڑے۔ آہ، میں وکٹر ہیوگو کے ساتھ یہ بےانصافی نہیں کر سکتا۔ میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مجھے اس دکان کی تلاش ہے جہاں وہ فورسیپس مل سکے جس کی مدد سے لوگوں کو کھینچ کر اس دنیا میں لایا جاتا ہے۔ کلکتہ میڈیکل کالج کے باہر مجھے اس طرح کی کچھ دکانیں نظر آتی ہیں۔ میں ٹرام کی پٹری کے بیچوں بیچ کھڑا آسمان پر نظر ڈالتا ہوں، آسمان جو ہمیشہ کی طرح بے رنگ مگر پراسرار ہے۔ آخر کار انسان کو اس کی منزل مل ہی جاتی ہے۔
وینس سرجیکل ہوم!
میں اندر داخل ہوتا ہوں۔
کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا آدمی سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہا ہے۔
’’آپ ڈاکٹر ہیں؟‘‘ وہ پوچھتا ہے۔
’’نہیں،‘‘ میں کہتا ہوں۔ ’’مگر مجھے ایک فورسیپس کی ضرورت ہے۔ کیا اس کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری ہے؟‘‘
’’ارے نہیں۔ یہ تو ہم نے آپ سے ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔‘‘
اس دکان کی الماریوں میں نقلی ٹانگیں اور ہاتھ رکھے ہیں۔ پیشاب اور دست کے مرتبان اورہاتھ پاؤں سے معذور لوگوں کے لیے اسٹول اور کرسیاں فرش پراِدھر ادھر بکھری پڑی ہیں۔ہر طرح کے آلات، ربر، پلاسٹک اور گلاس فائبر کے سازوسامان شوکیسوں کے اندر ترتیب اور بے ترتیبی سے سجے ہوے ہیں، دیواروں سے لٹک رہے ہیں۔ مجھے ایک آلہ خاص طور پر متاثر کرتا ہے جو کافی دھار والا اور قدرے مڑا ہوا ہے۔ شاید اس سے ہڈیاں کاٹی جاتی ہوں۔ اسے تو کسی بوچڑ کی دکان پر ہونا چاہیے تھا۔
قیمت بتاکر فورسیپس میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا گیا ہے مگر سیلزمین کی آنکھوں میں تذبذب ہے۔ خاموشی کے ساتھ وہ میرے چہرے کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ دکان کا بوڑھا مالک صاف شفاف دھوتی کرتا پہنے کیش کاؤنٹر پر بیٹھا ہے۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ رکھا ہے۔
’’واقعی۔۔۔‘‘ میں آلہ اٹھا کر دیکھتا ہوں۔ ’’واقعی اس کی شکل جتنی پیچیدہ، جتنی بھیانک ہے، اس کا اسٹیل اتنی ہی بے رحمی سے چمک رہا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے یہ سچ مچ ایک گھناؤنا کام کرنے کے قابل ہے۔‘‘
’’گھناؤنا کام؟‘‘ سیلزمین کا ردعمل فطری ہے۔ دکان کا مالک میری طرف تاکتا ہے۔
’’کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں،‘‘ میں چمٹے کے پیچ کو ڈھیلا کرتے ہوے، پھر کستے ہوے کہتا ہوں،جیسے اس کے لوہے کے حلقوں کو کسی بچے کے فرضی سر کے موافق بنانا چاہتا ہوں۔
’’کیوں نہیں،‘‘ سیلزمین کہتا ہے۔ ’’چھ سو روپے۔‘‘
میں پلٹ کر دکان کے اندر ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہوں۔ وہاں میں تنہا گاہک ہوں۔ میں دکان کے باہر تاکتا ہوں جہاں ٹرام کی روشن پٹریوں کے اوپر ایک لاغر رکشا والا اپنے رکشا پر ایک بھاری بھرکم عورت کو لادے تیزی سے گزر رہا ہے۔ مجھے صدیق عالم کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے کیا کہا تھا، وہ ایک انتہائی چالاک قسم کا انسان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرام کے اندر ٹکٹ کے پیسے تو کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ مگر جب آپ کی ضرورت واقعی اہم ہو، جب سچ مچ اس کی آپ کو ضرورت ہو، یہ صدیق عالم دور دور تک دکھائی نہیں دےگا۔ یہی اس کا کردار ہے۔
’’شاید اگلی بار میں اسے خرید لوں۔‘‘ میں فورسیپس کاؤنٹر پر واپس رکھ دیتا ہوں۔
بوڑھا اپنی پرانی عمارت کے نیچے کھڑا سڑک پر لڑکوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھ رہا ہے۔ پندرہ برس پہلے جب وہ رائٹرز بلڈنگ سے ریٹائر ہوا تھا تب اس سڑک پرکلکتہ امپروومنٹ ٹرسٹ کی جانب سے پودے لگائے جا رہے تھے جو اَب تناور درختوں میں بدل گئے ہیں اور اپنے پتے پھول اور پھل نیچے پھینکنے لگے ہیں۔ وہ جب ان لڑکوں کی عمر کا تھا تو یہ سڑک ایک پگڈنڈی کی شکل میں ایک تالاب کے کنارے واقع تھی جو سنگھاڑوں کی بیلوں سے نصف ڈھکا ہوا تھا اور جس کی جھاڑیوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگلی مرغ اور گلہریاں پکڑا کرتا تھا، مار آبی مارا کرتا تھا۔ تالاب اب اپنے سنگھاڑوں اور جھاڑیوں کے ساتھ غائب ہو چکا ہے اور اس کی جگہ خوبصورت دیدہ زیب کثیرالمنازل عمارتوں نے لے لی ہے اور وہ پگڈنڈی اب ایک کشادہ صاف ستھری سڑک میں بدل چکی ہے۔ کل ملاکر اب یہ شہر کا ایک بہت ہی متمول رہائشی علاقہ ہو گیا ہے جس میں سب سے پرانی عمارت اسی بوڑھے کی ہے جس میں آزادی کی افراتفری کے دوران مغربی پاکستان سے آکر بسے ہوے پنجابی اور سندھی اب بھی پچاس یا سو روپے ماہانہ کرایہ دیتے ہیں، کلب جاتے ہیں اور تین تین لاکھ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ اس عمارت کا مالک ہوتے ہوے بھی اب اس علاقے میں وہی سب سے غریب آدمی ہے۔ شہر میں ٹھنڈک کافی کم ہو گئی ہے۔ سامنے بادام کے پیڑ کے پتے سرخ ہوکر مرجھانے اور زمین پر گرنے لگے ہیں۔ دور دور کی گلیوں سے بچے پتھر اکٹھا کر کے اس پیڑ کے نیچے بادام توڑنے آیا کرتے ہیں۔لوگ اپنی کھڑکیوں سے حقارت کے ساتھ ان غلیظ بچوں کو گھورتے ہیں اور ان کے پتھروں سے خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ بوڑھا سر اٹھا کر بجلی کے تار کو دیکھتا ہے جو خودکشی کے واقعے کے بعد دو ہفتے قبل تک زمین سے پانچ فیٹ کی بلندی پر جھول رہا تھا مگر اب پھر سے اسے برابر کر دیا گیا ہے۔ بہت اوپر بالکنی پر اس کی بہو نہا کر کپڑے پسار رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنا لڑکا آتا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کشمشی رنگ کی ایک منکی کیپ پہن رکھی ہے اور پان چبا رہا ہے۔ بوڑھے کو حیرت ہوتی ہے۔ وہ پان تو کھایا نہیں کرتا اور پھر آج تو اتنی سردی بھی نہیں، پھر یہ منکی کیپ کیوں؟
’’ایک ہی سڑک پر دو طرح کی روشنیوں کا انتظام! واقعی میں نے تو کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔‘‘ اس کا لڑکا برقی تار والے کھمبے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس کی عمارت کے عین نیچے ایک بلب کے ساتھ کھڑا ہے اور پھر سڑک پار اس اونچے کھمبے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا اوپر کا سرا عمودی ہو کر ایک بڑے سے سوڈیم ویپر لیمپ کو تھامے ہوے ہے۔ اس بڑے کھمبے کا تعلق زمین دوز تاروں سے ہے اور یہ کھمبے پچھلے ہی سال اس سڑک کی دوسری جانب کھڑے کیے گئے ہیں۔ شاید انھیں لگانے کے بعد یہ تار والے کھمبے بھلا دیے گئے ہیں۔ ’’ہمیں سرکار کی توجہ اس طرف مبذول کرانی چاہیے۔‘‘
بوڑھا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسے معلوم ہے اس کا لڑکا اپنے کالج کے دنوں سے (جہاں علم ریاضی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا) کچھ زیادہ ذہنی عدمِ توازن کا شکار ہے۔ (اس نے بی ایس سی کے آخری سال میں اچانک کالج جانا بند کر دیا تھا۔) سائنس کا طالب علم ہوتے ہوے بھی نئی نئی زبانوں کو سیکھنے کے سلسلے میں اس کی صلاحیت حیرت انگیز تھی۔ اپنے کتاب بینی کے جنون کی حد تک شوق کے سبب وہ نہ صرف ان ساری زبانوں کو لکھ اور پڑھ سکتا تھا جو کلکتہ کی سڑکوں پر بولی جاتی تھیں بلکہ اس نے کسی کی رہنمائی کے بغیر فرانسیسی اور جرمن میں بھی اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ کبھی اس کا زیادہ وقت کلکتہ کی مختلف لائبریریوں میں گزرتا تھا مگر گذشتہ ایک سال سے اس نے کتابوں سے پوری طرح کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ بوڑھے کو پتا ہے خاموشی ہر وقت اس کے ساتھ پیش آنے کا صحیح طریقہ نہیں، مگر اسے اس کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لڑکا پان چباتا ہوا قدیم زمانے کی نشیبی سیڑھیاں طے کرتے ہوے تیسری منزل پر (جو اس عمارت کی آخری منزل بھی ہے) اپنے فلیٹ پر پہنچتا ہے جہاں بالکنی میں اس کی بیوی پچی کاری کے فرش پر کھڑی اپنے گیلے بالوں کو دھوپ میں سکھا رہی ہے اور پلاسٹک کی کنگھی سے ان کی لٹوں کو درست کر رہی ہے۔ یہ بالکنی موجودہ زمانے کی بالکنیوں کے تناسب سے کافی بڑی ہے اور اسے بالکنی سے زیادہ بندٹیرس کہا جا سکتا ہے۔
’’کیا بات ہے، تم ہمیشہ اپنے بالوں پر کنگھی کرتی رہتی ہو؟‘‘ وہ کہتا ہے، پھر اس کے بالوں کو اٹھاکر دیکھتا ہے جو اس کے کنوارے سڈول کولھوں تک لٹک رہے ہیں۔ ان سے ایک عجیب سی تیزخوشبو آ رہی ہے جیسے اس کا تعلق بدلتے موسم سے ہو۔ ’’ویسے تمھارے بال کافی خوبصورت ہیں، ڈیلا کے بالوں کی طرح۔‘‘
’’میری اور بھی چیزیں خوبصورت ہیں،‘‘ وہ مسکرا کر کہتی ہے۔ ’’اور یہ ڈیلا کون ہے؟‘‘
’’جانے دو اسے۔‘‘ وہ منکی کیپ سر سے اتار کر کونے کی میز پر پھینکتا ہے۔وہ دیکھتی ہے اس کے سر پر پسینہ جم رہا ہے۔ ’’وہ ایک کہانی کی فرضی کردار ہے جو ہماری ہی طرح غریب ہے اور اپنے شوہر کو تحفہ دینے کے لیے اپنے بال بیچ ڈالتی ہے۔‘‘
’’تحفہ۔۔۔‘‘ اس کی بیوی کو کچھ یاد آ جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سے ایک سر بہ مہر خاکی منیلا لفافہ نکال کر لاتی ہے جو کافی بڑا ہے اور ایک حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح پھولا ہوا ہے۔ لفافہ کافی وزنی بھی ہے۔
’’اسے کوئی تمھارے لیے چھوڑ گیا ہے۔‘‘
لفافے کا منھ سیلو ٹیپ سے بند ہے جسے قینچی سے کاٹنے پر اندر سے وہی فورسیپس نکل آتا ہے جسے اس نے دوروز قبل کالج اسٹریٹ پر وینس سرجیکل ایمپوریم میں دیکھا تھا۔ اس کے ہینڈل سے ایک کارڈ نائلن کے تاگے کے ذریعے منسلک ہے جس پر مارکر پین سے لکھا ہے ’’To whom it may concern‘‘
آگے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، نہ کارڈ پر کسی کا نام ہے۔
’’تم نے نام نہیں پوچھا؟‘‘
’’وہ بہت جلدی میں تھا۔‘‘
وہ فورسیپس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔
’’کیسا تھا وہ؟‘‘
’’اوسط قد کا۔‘‘
’’بال؟‘‘
’’کالے، چھوٹے چھوٹے ترشے ہوے، تمھاری طرح۔‘‘
’’عینک؟‘‘
’’تھی۔‘‘
’’مونچھیں؟‘‘
’’نہیں تھیں۔۔۔شاید تھیں۔۔۔میں نے غور نہیں کیا۔‘‘
’’عمر؟‘‘
’’تم کیا سمجھتے ہو، ایک جھلک میں اتنا سب کچھ دیکھنا ممکن تھا؟‘‘ اس کی بیوی بولتی ہے۔ ’’اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی، مجھے یہ لفافہ تھمایا اور مجھ سے کہا۔ ’’اچانک اس طرح دروازہ کھولنا ٹھیک نہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہنگر فورڈ اسٹریٹ پر ایک فلیٹ کے اندر کچھ غلط لوگ گھس آئے تھے، بلکہ انھوں نے ایک بوڑھی عورت کا خون بھی کر دیا۔‘‘
آہ، وہ صدیق عالم کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھ کر فورسیپس سے کھیلنے لگتا ہے۔ یہ وہ آرام کرسی ہے جس پر بیٹھ کر اس کے باپ دادا بوڑھے ہوے۔ یہ آرام کرسی اس نے ستیہ جیت رائے کی ہر دوسری فلم میں دیکھی تھی، بلکہ کبھی کبھی تو اسے ایسا لگتا جیسے یہ کرسی ستیہ جیت رائے کی کسی فلم کے سیٹ سے اٹھا کر لائی گئی ہو۔
’’یہ چیز میری سمجھ سے بالا تر ہے۔‘‘ اس کی بیوی کنگھی سے بالوں کو نوچ نوچ کر ایک گچھے کی شکل میں جمع کر رہی ہے تاکہ اس پر تھوک سکے۔ بالوں کا تھوکا ہوا گچھا نیچے سڑک پر کھڑے اس کے سسر کے سامنے گرتا ہے مگر اس کی کمزور آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ان کتے کے پلوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے جو اس کی پھٹی ایڑیوں کو سونگھنے کہیں سے آ نکلے ہیں۔ تین ماہ قبل ان کی ماں، جو اس عمارت کی بالکنیوں سے پھینکا ہوا پس خوردہ کھانے اپنے نوزائیدہ بچوں کے ساتھ آیا کرتی تھی، اسی سڑک پر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ڈمپر کے نیچے آ گئی تھی۔
’’تمھیں اس چمٹے کو دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہوگی۔‘‘ اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنے سر کی پشت پر پھیلاکر آرام کرسی پر جھولتے ہوے وہ مسکرا رہا ہے، گاہے بگاہے فورسیپس کو فرش سے اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ ’’انسان جب کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ خود اپنے سوالوں میں گھر جاتا ہے۔ اپنے لیے یہ پنجڑا وہ خود تیار کر تا ہے اور اکثر ساری عمر اس پنجڑے کے اندر ہی جیتاہے کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے۔‘‘
سبیتا اس کی بات سن نہیں رہی ہے۔ وہ بالکنی سے بہت دور گوسابہ میں خلیج بنگال کی کڑی دھوپ میں کھڑی ہے جہاں کھاڑی کا نمکین پانی کنارے کی کیچڑ پر ہلکورے لے رہا ہے، انھیں فلس کی شکل میں کاٹ رہا ہے، ان کے پشتوں کی کنکریٹ کی دیوار اور سیڑھیوں کے زیریں حصوں پر سیپ چپکا رہا ہے۔ وہ ان سرخ پیڑوں کو دیکھ سکتی ہے جن کے آس پاس رائل بنگال ٹائیگر دہاڑتے رہتے ہیں۔ گرچہ وہ بالکل سانولی ہے مگر ایک اچھے ناک نقشوں والی ایک بھرے پرے بدن کی عورت ہے اور اس کے چہرے میں، جیسا کہ مقامی لوگ کہا کرتے ہیں، کافی نمک ہے۔ اس کا غریب باپ سندر بن کے پانی پر جال پھیلایا کرتا ہے اور پھیلاتا رہےگا جب تک کوئی گھڑیال اسے کھینچ کر پانی کے اندر نہ لے جائے یا کوئی کوبرا نہ ڈس لے۔ اس کی ماں اسے یاد نہیں۔ وہ ریلنگ سے مڑ کر دیکھتی ہے۔ وہ آرام کرسی پر پہلے کی طرح پینگیں لیتے ہوے اسے میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے۔
’’تم کچھ سوچ رہی تھیں، سبیتا؟‘‘
’’کھانا لگادوں؟‘‘
’’تمھیں صرف کھانے کی ہی فکر کیوں رہتی ہے؟‘‘
’’اور میرا کام کیا ہے۔‘‘ وہ کمرے کے اندر سے ہوتے ہوے باورچی خانے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ چمٹے کو زمین پر رکھ کر بنگلہ اخبار اٹھا لیتا ہے جو اس کا باپ صبح سے شام تک پڑھتا رہتا ہے۔ اخبار دھوپ میں پڑے پڑے گرم ہو گیا ہے۔ اسے اخبارکے دفتر کا پتا چاہیے جو اسے آخری صفحے کے بالکل نیچے منحنی حرفوں میں لکھا نظر آتا ہے۔ اسے اس اخبار کے مدیر کو ایک خط لکھنا ہے۔ ایک احتجاجی خط، ایک سڑک کے بارے میں جہاں دو طرح کی روشنیوں کا انتظام ہے جب کہ کلکتہ میں ایسی سینکڑوں گلیاں ہیں جن کے کھمبوں پر بلب مہینوں تک نہیں جلتے۔
’’جنابِ عالی!‘‘ وہ ایک پوسٹ کارڈ پر لکھتا ہے۔ ’’میں بالی گنج سیکنڈ لین کا رہنے والا ہوں۔ یہ ایک صاف ستھری ذیلی سڑک ہے جس پر دو طرح کی روشنیوں کا انتظام ہے۔۔۔‘‘
’’رک جاؤ، تم یہ خط نہیں لکھ سکتے۔‘‘
آہ!یہ صدیق عالم، وہ سمجھتا ہے چونکہ وہ قلمکار ہے وہ خط بھی اچھا لکھ سکتا ہے۔ کہانی لکھنا اور بات ہے مگر اخبار کے مدیر کو خط لکھنا، وہ بھی ایک احتجاجی خط جس کا مقصد شہر بلدیہ کے انتظام میں عملاً ایک تبدیلی، ایک بہتری لانا ہے، یہ ایک کہانی کار کے بس کی بات نہیں جس کی دنیا بس تصورات کے فریم میں بند ہوتی ہے۔ میں نے اس کا لکھا ہوا خط چھین لیا ہے، اس کے پر زے پرزے کر دیے ہیں۔ میں نے ایک نیا پوسٹ کارڈ لے کر ایک دوسرا خط لکھا ہے جس کے لیے مجھے سبیتا سے اس کا قلم ادھار مانگنا پڑا ہے۔ یہ اس کی شادی کا تحفہ ہے۔اس سے وہ گوسابہ اپنا گھر خط لکھا کر تی ہے جس کا جواب اسی ترتیب سے آیا کرتا ہے۔
میں نے خط کو اپنے نکڑ کے لیٹر بکس کے اندر ڈال دیا ہے جو ایک پرانے پیڑ کے تنے سے لٹک رہا ہے۔ یہ لیٹر بکس سرخ رنگ کا ہے اور اس پرچڑیوں کی بیٹ کی زیبرا لکیریں ہیں۔ اب میں ہر روز بےچینی سے اخبار کے خطوط کے کالم کا مطالعہ کرتا ہوں۔ پندرہ دن گزر گئے ہیں، مگر مجھے وہ خط اخبار میں دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے دو پوسٹ کارڈ اور بھی چھوڑے ہیں اور آخری پوسٹ کارڈ بذات خود بالی گنج پوسٹ آفس میں ڈال آیا ہوں۔ گرچہ بعد کے دونوں خطوط میں زبان تھوڑی سی بدل گئی ہے مگر میرا خیال ہے مضمون کا متن اپنی جگہ قائم ہے۔ میں نے اپنے آخری خط کی کاپی اپنے علاقے کی کاؤنسلر کو بھی دی ہے۔ وہ ایک غیر شادی شدہ عورت ہے، کمیونسٹ پارٹی کی ممبر ہے، اپنی ذاتی ماروتی وین میں گھوم گھوم کر غریبوں کے مسئلے حل کرتی ہے۔ غریب جنھیں ڈھونڈنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ ایک بڑی تعداد میں آپ کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں، کووں کی طرح، جنھیں جس روشنی میں بھی دیکھو وہ کوے ہی نظر آتے ہیں۔
’’یہ تو اس سڑک کے لیے اچھا ہی ہے نا۔ آپ کو تو ممنون ہونا چاہیے۔‘‘ وہ مسکراتی ہے۔
’’یقیناً یہ خوشی کی بات ہوتی اگر تمام سڑکوں پر اس طرح کا انتظام ہوتا اور پھر ان جگہوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جہاں سالوں سال روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا؟‘‘
’’کیا کلکتہ میں ایسی کوئی سڑک بھی ہے؟ اپنے علاقے میں میں نے توخود سے ہر جگہ روشنی کا انتظام کیا ہے۔ جانے آپ کس جگہ کی بات کر رہے ہو۔‘‘
وہ واقعی ایک قابل سیاست دان ہے جس کے پاس ہر موقعے کے لیے مناسب جواب موجود ہے۔ وہ وین کا شیشہ ڈھکیل کر بند کرنا چاہتی ہے کہ اس کے بغل میں بیٹھا ہوا آدمی اس کے کان میں کچھ سرگوشی کرتا ہے۔ میں اس آدمی کو پہچانتا ہوں۔وہ ہمارے علاقے میں بلاوجہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے اور اسی طرح آوارہ گردی کرتے کرتے ایک دن بڑا لیڈر بن جائےگا۔ کاؤنسلر مسکراکر میری طرف دیکھتی ہے۔
’’پھر بھی میں اس پر غور کروں گی،‘‘ وہ کہتی ہے اور گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے اب کچھ ہونے والا نہیں، ان غریبوں کی طرح، مگر میں کوشش جاری رکھتا ہوں۔ میں نے اخبار کو ایک اور خط دیا ہے اور تب وہ خط شائع ہو جاتا ہے گرچہ یہ میرا آخری خط نہیں ہے۔ شاید یہ میرا دوسرا خط ہے جسے میں نے پہلے خط کے ایک ہفتے بعد لکھا تھا۔ مجھے خط کے کالم میں اپنا نام دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی، پھر بھی میں اسے سبیتا کو دکھاتا ہوں۔ وہ خط کو سانس تھام کر شروع سے آخر تک پڑھ جاتی ہے۔ وہ میرے نام پر اپنی انگلی رکھ کر مسکراتی ہے جیسے اسے محسوس کر رہی ہو۔ اس میں اس کی شادی کی انگوٹھی چمک رہی ہے۔
’’مجھے یقین نہیں ہوتا یہ تم نے لکھا ہے،‘‘ وہ کہتی ہے۔ ’’پھر بھی میں خوش ہوں کہ تم نے واقعی یہ خط لکھا ہے۔‘‘
جانے اس کے بولنے کے انداز میں ایسی کیا بات ہے کہ میں اخبار اٹھا کر خط کو پڑھنے لگتا ہوں۔ اوہ، اوہ، واقعی، یہ تو میرا لکھا ہوا خط ہے ہی نہیں۔ یہ تو اسی ملعون قلمکار کا کارنامہ ہے۔ یہ تو وہی تحریر ہے، وہی خط ہے جسے میں نے پر زے پرزے کر دیا تھا۔
’’جناب عالی! میں بالی گنج سیکنڈ لین کا رہنے والا ہوں۔یہ ایک صاف ستھری ذیلی سڑک ہے جس پر دو طرح کی روشنیوں کا انتظام ہے۔۔۔‘‘
آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ صدیق عالم، مجھے اس کے ساتھ ایک آخری فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں اس کی تلاش میں اس کی عمارت تک جاتا ہوں مگر اس کے گھپ تاریک زینے کی پہلی لینڈنگ پر ہر بار مجھے ایک بیمارخارش زدہ کتا بیٹھا نظر آتا ہے۔ اس کے بدن کی رستی ہوئی خارشوں سے ایک عجیب دم گھونٹ دینے والی بدبو خارج ہوتی رہتی ہے۔ سیڑھی کے اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھوں سے جانے کیوں مجھے لگتا ہے اسے میرا وہاں آنا پسند نہیں اور اگر میں نے اسے پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ گرچہ ہر بار میں وہاں سے لوٹ آتا ہوں مگر اس کتے کے بدن کی بو گھنٹوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پھر ایک دن میں دیکھتا ہوں، وہ تار اور کھمبے وہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں۔ مجھے وہ کاؤنسلر کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ صرف صدیق عالم اوور سیئر سے تھوڑی دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک بار میرے اندر اس کے پاس جانے کی خواہش جاگتی ہے لیکن دوسرے ہی لمحے مر جاتی ہے۔ جہنم میں جائے وہ، میں سوچتا ہوں۔ وہ ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں اتنی سنجیدگی سے سوچا جائے۔دنیا میں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ہی غیر اہم ہوتی ہیں مگر ہماری توجہ کے سبب ایک خاص اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔
صدیق عالم سڑک سے گزر کر اوور سیئر کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اور اس سے بات کر رہا ہے۔ اوور سئیراسے کچھ سمجھا رہا ہے، پھر خود اثبات میں سر ہلاتا ہے۔ وہ واپس چلا جاتا ہے اور پیڑوں کے نیچے ٹھنڈ کی ماری چڑیوں کی بیٹ سے داغدار فٹ پاتھ پر قدم رکھتا ہوا غائب ہو جاتا ہے۔
وہ لوگ تار اور کھمبے ہٹا کر جا چکے ہیں۔ میں بالکنی کے جنگلے سے جھک کر نیچے دیکھتا ہوں۔ ہماری عمارت کے سامنے سے کھمبا اکھاڑ لیا گیا ہے اور اب اس جگہ زمین اس طرح ادھڑی پڑی ہے جیسے قرون وسطی کے کسی جاپانی سامورائی نے ہاراکیری کرکے اپنی انتڑیاں باہر نکال لی ہوں۔ تار اور کھمبے کی عدم موجودگی میں ہماری بالکنی کافی اونچی اور خطرناک نظر آ رہی ہے۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ وہاں کنویں کے اندر کا سا گہرا اندھیرا ہے۔ مجھے تھوڑی دیر تک اس کنویں میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، پھر دھیرے دھیرے ایک چہرہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ صدیق عالم کا چہرہ ہے۔ پھر اس چہرے کے پیچھے کے مناظر ابھرتے ہیں۔ وہ پیڑو ں کے نیچے چڑیوں کی بیٹ کے نشانات پر چلتے ہوے مڑمڑ کر میری طرف تاک رہا ہے، مسکر ا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ ایک خاص منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی کہانی کو اس کے انجام تک اس کی مرضی کے مطابق چلنے نہیں دوں گا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوں اور میز کی دراز سے چمٹا باہر نکال کر واپس بالکنی پر نکل آتا ہوں۔ نیچے سڑک اپنے دونوں کنارے دور تک سنسان پڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سڑک زیادہ تر سنسان رہتی ہے۔میں جنگلے کے اوپر جھک کر چمٹا نیچے پھینک دیتا ہوں۔چمٹے کے سڑک سے ٹکرانے کی آواز میرے کانوں تک آتی ہے۔ اتنی بلندی سے تارکول کی سڑک پر پڑا ہوا اسٹیل کا چمٹا عجیب نظر آ رہا ہے جیسے وہ کوئی مشینی پرندہ ہو اور ابھی ابھی اپنے پر پھیلا کر اڑ جائےگا۔ ایک دو کار ہارن بجائے بغیر گزر جاتی ہے۔ ایک تنہا راہگیر کہیں سے آ نکلتا ہے۔اس کی نظر چمٹے پر پڑتی ہے۔ اس نے ایک کافی دبیز سفید رنگ کا ریشے دار سویٹر پہن رکھا ہے جس کے سبب وہ انسان کم اور انٹارٹیکا کا ایک جانور زیادہ نظر آ رہا ہے۔ وہ فورسیپس کو اٹھا کر اپنے چاروں طرف سوالیہ نظروں سے تا کتا ہے، پھر چہرہ اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھتا ہے۔ میں چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا ہوں۔ وہ چمٹا لیے ہوے، الٹ پلٹ کر حیرت سے اس کا معائنہ کرتے ہوے چلا جاتا ہے۔ آہ، مجھے اس شاطر کہانی کار کو حیرت میں ڈالنا ہوگا، اسے اسی کی چال میں مات دینا ہوگی۔ میں اپنے کمرے کے اندر جاتا ہوں۔ دوپہر کا کھانا کھا کر سبیتا ہلکی نیند سورہی ہے۔اس کا بھاری سینہ سانس کے زیرو بم کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ میں اس کے داہنے پستان پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگتا ہوں۔ سبیتا آنکھیں کھولتی ہے، مسکراتی ہے۔ میں اس کے داہنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر چومتا ہوں جس میں اس نے شگن کے سنکھ اور لوہے کے کڑے پہن رکھے ہیں۔ وہ اپنا سر میرے کندھے سے لگا دیتی ہے۔
’’تم دروازہ کیوں نہیں بند کر لیتے؟‘‘ سبیتا شرما کر کہتی ہے۔
’’اس کی کیا ضرورت ہے۔‘‘ میرے بائیں ہاتھ کی انگلیاں اکٹوپس کی طرح اس کی ناف سے گزر کر نیچے جا رہی ہیں۔ مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ اپنی ٹانگوں کے بیچ گیلی ہو چکی ہے۔
’’گھبراؤ مت۔ گھر پر کوئی نہیں،‘‘ میں اس کے صحت مند ننگے پستانوں کو چومتے ہوے کہتا ہوں جو بلاؤز کے کٹے ہوے گلے سے ابھرے ہوے ہیں۔
سبیتا لیبر روم کی میز پرلیٹی دردِ زہ سے کراہ رہی ہے۔ میں اسے دلاسا دے رہا ہوں جب ڈاکٹر اندر آتا ہے۔ سفید ماسک سے نکلی ہوئی عینک کے شیشوں کے اندر سے اس کی آنکھیں میری طرف نہیں تاکتیں۔ وہ کافی مصروف بھی دکھائی دے رہا ہے۔
’’ہمیں مریض کو اوٹی میں لے جانا ہوگا،‘‘ وہ میری طرف توجہ دیے بغیر نرس سے مخاطب ہوتا ہے اور اسٹیتھوسکوپ کو لا پروائی سے ہلاتے ہوے اوٹی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اوٹی کے دروازے پر میں اسے جا لیتا ہوں۔
’’یہ کیس تو نارمل ڈیلیوری کا ہے نا ڈاکٹر، جیسا کہ مجھے شروع سے بتایا گیا تھا؟‘‘ میں اس سے کہتا ہوں۔
’’بچہ اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا، ‘‘ڈاکٹر کہتا ہے۔’’ اور پھر پیڑو کے مقابلے میں بچے کا سر بہت بڑا ہے۔ ہمیں فورسیپس کا استعمال کرنا ہوگا۔‘‘
’’ارے نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔‘‘ میں سہم کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری دونوں کنپٹیوں پر کوئی ٹھنڈی چیز رکھ دی گئی ہو۔ ’’میرا خیال ہے کہیں پر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ صبح تک تو سب ٹھیک تھا۔ اچانک یہ سب کچھ کیسے بدل گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟‘‘
’’اور کیوں نہیں ہو سکتا؟‘‘ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر اپنے چہرے سے ماسک ہٹا تا ہے۔
’’تم!‘‘
’’ہاں، میں۔‘‘ اس نے ماسک واپس لگا لیا ہے اور اب اس کے اندر سے اس کی آواز آ رہی ہے۔ ’’اور تم سمجھ بیٹھے تھے کہ تم اپنی زندگی کی کہانی خود لکھ سکتے ہو۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ دیکھو تم نے اپنا ستیاناس کر لیا نا؟ تم نے مجھ پر اعتبار نہ کیا، تم نے میرا بھیجا ہوا تحفہ سڑک پر پھینک دیا۔ یہی وہ فورسیپس ہے نا جسے تم چمٹا کہتے تھے؟‘‘ وہ اپنے ایپرن کی جیب سے چمٹا نکال لیتا ہے۔ ’’تم نے جلد بازی کی۔ تم نے مجھ سے بازی لے جانا چاہا، اپنے خالق سے۔ تم نے سوچا تم صفحات سے باہر بھی سانس لے سکتے ہو، اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے ہو۔ تم نے میرے انتظام میں جو انتشار پیدا کیا اب اس کا نتیجہ تمھارے سامنے ہے۔ یہ فورسیپس۔۔۔‘‘ وہ فورسیپس میرے چہرے کے سامنے لٹکا دیتا ہے۔ اس کا اسٹیل راہداری کی ٹیوب لائٹ کی تیز روشنی میں بے رحمی سے چمک رہا ہے۔ ’’تمھارا بچہ، تم نے یہ بالکل نہ سوچا اسے کیا چاہیے، کہ اس کی اپنی کوئی مرضی بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے تم ساری عمر لڑتے آئے تھے، تم نے صرف مجھ سے جیتنے کی ضد میں اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔۔۔‘‘
اوٹی کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس کی سرخ بتی جل اٹھی ہے۔ میں ٹھنڈی دیوار سے چپکا کھڑا ہوں۔ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ میرے سامنے اسٹریچر کے پہیے گھومنے لگتے ہیں۔ اس اسٹریچر پر سبیتا درد کی شدت سے نیم بے ہوش لیٹی کراہ رہی ہے۔ گرچہ اس کی آنکھیں بند ہیں مگر جانے کیوں مجھے لگتا ہے اسے میری موجودگی کا علم ہے۔ اوٹی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسٹریچر کسی قسم کی آواز پیدا کیے بغیر اندر چلا جاتا ہے۔ اب میں باہر اکیلا کھڑا ہوں۔ نہیں، شاید کوئی میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ یہ میرا باپ ہے جو آ گیا ہے اور لکڑی کے ایک بنچ پر خاموش بیٹھا ہے۔ مجھے اس کی موجودگی عجیب سی لگتی ہے جیسے وہ وہاں موجود نہ ہو، صرف میرا اضافہ ہو گیا ہو۔ میرے سر کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس درد کے سبب میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں، مجھے دیوار کافی بھاری لگ رہی ہے جیسے وہ میرے سہارے کھڑی ہو۔ اندر سبیتا کا دردِ زہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔
’’تم ٹھیک تو ہو؟‘‘ میرے باپ کی آواز مجھے اس دیوار سے کھینچ کر باہر نکالتی ہے۔ اوٹی کے بلب کی سرخی میری آنکھوں سے رس رہی ہے۔ میں سر موڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہوں اور گرچہ وہ بنچ پر دیوار سے لگا بیٹھا ہے میں اسے دیکھ نہیں پاتا اور لڑکھڑا تے ہوے باہر جانے لگتا ہوں۔ نرسنگ ہوم کے باہر ایک ایمبولنس کار کھڑی ہے جس کی روشنی تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ ایک مریضہ اس نرسنگ ہوم سے کسی دوسری جگہ منتقل کی جا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر آکسیجن کا ماسک لگا ہے جس کے اوپر سے اس کی آنکھیں اس طرح نظر آ رہی ہیں جیسے وہ اپنے ہی اندر مرکوز ہوں۔ میں نے سڑک تیزی سے پار کی ہے۔ آسمان پر آدھی رات کا چاند دہک رہا ہے جو ہمارے محلے کی کشادہ سڑک تک میرا پیچھا کرتا ہے اور میرے رکتے ہی پیڑوں کے اوپر تھم جاتا ہے۔ ہماری عمارت کا صدر دروازہ ہمارے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں سیڑھیوں کو پھلانگتے ہوے اپنے فلیٹ کی لینڈنگ پر آتا ہوں۔ درد سے پھٹتے سر کو ایک طرف گراکر میں نے جیب سے کنجی نکالی ہے اور داخلے کا دروازہ کھول کر کنجی کو اس کے سوراخ سے لٹکتا چھوڑ دیا ہے۔
اب میں چاند سے روشن بالکنی پر اس کاجنگلہ تھامے کھڑا ہو ں اور دور تک نظر آنے والی عمارتوں کے اندر شاید واحد شخص ہوں جو جاگ رہا ہے۔رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے۔ نیچے سڑک اپنے دورویہ پیڑوں کے ساتھ سنسان پڑی ہے۔ میں ریلنگ پر جھک کر ایک گہری سانس لیتا ہوں۔ ہوا میں کٹھل چمپا کی تیز خوشبو ہے۔ آسمان پر روئی کے گالوں کی شکل کے بادل بکھرے ہوے ہیں جیسے بےشمار پھاہے نہ نظر آنے والے زخموں پر رکھے ہوں۔ میں نے اپنے داہنے ہاتھ سے جنگلے کو تھام رکھا ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اس مادی دنیا سے باہر نکل آیا ہوں۔ جانے کتنا وقت گزر گیا ہے، جب ایک تیز آواز سے میری محویت ٹوٹ جاتی ہے۔ فون کی گھنٹی کمرے کے اندر بج رہی ہے۔ میں جنگلے کو پھلانگ کر بالکنی کی دیوار کے باہری سرے پر قدم جماتا ہوں اور مڑکر تاکے بغیر بھی سمجھ سکتا ہوں ہمارے فلیٹ کے دونوں نیم تاریک کمرے اپنی بجھی ہوئی آنکھوں سے میری طرف تاک رہے ہیں۔ فون کی گھنٹی لگاتار بجتی رہتی ہے۔ جانے کتنا وقت گزر جاتا ہے یہاں تک کہ میں اسے بھول جاتا ہوں۔ جب مجھے دوبارہ اس کی یاد آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں فون کی گھنٹی رک چکی ہے اور ایک گہرے سناٹے نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، ایک ایسا سناٹا جو میرے کانوں میں کچھ کہنے کے لیے بےچین ہے۔ میں غور سے سننے کی کوشش کرتا ہوں مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ میں سر اٹھا کر دیکھتا ہوں، آسمان پر روئی کے پھاہے ہوا کی زد میں آکر رینگنے لگے ہیں اور چھتوں پر دور تک سوکھنے کے لیے ٹنگے ہوے کپڑوں نے پریت آتما کی طرح لہرا نا شروع کر دیا ہے۔ جنگلے سے میری انگلیوں کی گرفت ہٹ گئی ہے اور اب میں بغیر کسی سہارے کے دیوار پر اپنی جگہ کھڑا ہوں جیسے میں اس پرانی عمارت کا ایک بےجان حصہ ہوں ، پرنالے کے طور پر بنایا ہوا کوئی انسانی ڈھانچہ جس کی شرمگاہ سے برسات کا پانی باہر آتا ہے۔
بےجان انسانی ڈھانچے نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔اس نے ایک آخری نظر نیچے بادام کے پیڑ پر ڈالی ہے۔ پیڑ کی ڈالیاں سوڈیم لیمپ کی تیز روشنی میں سونے کی طرح دمک رہی ہیں۔ ان کے زیادہ تر پتے جھڑ چکے ہیں اور ٹہنیوں کے بیچ رکھا ہوا گھونسلا ویران ہے۔
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.