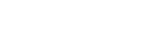واپسی کا ٹکٹ
انسان نے انسان کو ایذا پہنچانے کے لیے جو مختلف آلے اور طریقے اختیار کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے ٹیلی فون! سانپ کے کاٹے کا منتر تو ہوسکتا ہے مگر ٹیلی فون کے مارے کو تو پانی بھی نہیں ملتا۔
مجھے تو رات بھر اس کمبخت کے ڈر سے نیند نہیں آتی کہ صبح سویرے نہ جانے کس کی منحوس آواز سنائی دےگی۔ دو ڈھائی بجے آنکھ لگ بھی گئی تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کی گھنٹیاں اور گھنٹے گھڑیال بیک وقت بجنے شروع ہوگیے۔ مندروں کے پیتل کے بڑے بڑے گھنٹے، پولیس کے تھانے کا گھڑیال، دروازوں کی بجلی والی گھنٹیاں، سائیکلوں کی ٹرنگ ٹرنگ، فائر انجنوں کی کلینگ کلینگ اور جب آنکھ کلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اس غیر وقت رات کو کس کا فون آیا ہے؟ ضرور ٹرنک کال ہوگی۔ پل بھر میں نہ جانے کتنے وہم دل دھڑکاتے ہیں۔ ایک دوست مدراس میں بیمار ہے۔ ایک رشتہ دار لندن اور بمبئی کے درمیان ہوائی جہاز میں ہے۔ بھتیجے کا میٹرک کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔
میں فون اٹھاکر کہتا ہوں، ’’ہلو۔‘‘ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آتی ہے، ’’چنی بھائی، کیم چھو۔‘‘ میں کہتا ہوں کہ یہاں نہ کوئی چنی بھائی ہے نہ کیم چھو۔ مگر وہ کہتا ہے، ’’چنی بھائی۔ ٹاٹا ڈلیز ڈار پر جا رہا ہے۔‘‘ میں کہتا ہوں، ’’جانے دو۔‘‘ وہ گجراتی میں گالی دے کر کہتا ہے، ’’کیسے جانے دیں۔۔۔ برٹش الیکٹرک کے سودے میں پہلے ہی گھاٹا کھا چکے ہیں۔‘‘ میں سمجھاتا ہوں کہ ’’دیکھو بھائی میں چنی بھائی نہیں ہوں۔‘‘
’’اوہ!‘‘ ادھر سے آواز آتی ہے جیسے ایک دم ٹائر میں سے ہوا نکل گئی ہو، ’’تم چنی بھائی نتھی چھو۔‘‘ میں پوچھتا ہوں، ’’آپ کو کون نمبر چاہیے۔‘‘ وہ کہتا ہے، ’’ایٹ۔۔۔ سیون۔۔۔ ایٹ۔۔۔ سکس۔۔۔ سکس۔۔۔‘‘ میں کہتا ہوں، ’’یہ تو ایٹ سکس۔ ایٹ سیون، سیون ہے۔‘‘ وہ کہتا ہے، ڈانٹ کر، ’’تو پہلے ہی کیوں نہیں بولتے رونگ نمبر ہے۔‘‘ میں کہتا ہوں، ’’اچھا بھئی میرا ہی دوش ہے۔ اب شما کرو۔‘‘ اور فون رکھ دیتا ہوں۔ اور نیند کو واپس بلانے کے لیے بھیڑیں گننا شروع کر دیتا ہوں۔
اور پھر صبح اٹھ کر تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کا سلسلہ ہی شروع ہو جاتا ہے، ’’آپ مجھے نہیں جانتے۔ آپ کے پرانے وطن پانی پت کے قریب جو قصبہ ہے ریواڑی، وہاں سے آیا ہوں، فلم کمپنی میں ہیرو بننے۔۔۔‘‘
’’مجھے آپ سے اپائنٹ منٹ چاہیے۔ اپنی کہانیاں سنانا چاہتا ہوں۔‘‘
’’اگلی اتوار کو ہماری انجمن کا سالانہ جلسہ اور مشاعرہ ہے، آپ کو آنا ہی ہے پڑےگا۔۔۔ آپ کے نام کااعلان پہلے ہی کر چکے ہیں۔۔۔‘‘
’’پرچہ پریس میں رکا پڑا ہے۔ صرف آپ کے مضمون کے انتظار میں۔۔۔‘‘
’’دیکھیے۔ آپ مجھے نہیں جانتے۔ لیکن کیا آپ مجھے کرپا کرکے راج کپور کا ایڈریس دے سکتے ہیں؟‘‘
کل سویرے کی بات ہے کہ یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجی۔۔۔ میں نے ہمت کرکے فون اٹھایا، ’’ہیلو۔۔۔‘‘ میں نے کہا۔ حالانکہ ٹیلی فون کی ڈائرکٹری حکم دیتی ہے کہ ’’ہیلو‘‘ مت کہو۔
’’ہیلو۔‘‘ دوسری طرف سے بڑے ہی یورپین انداز کی آواز آئی۔ میں سمجھا کوئی امریکن یا انگریز بول رہا ہے۔ پھر اس نے انگریزی میں پوچھا، ’’کیا میں خواجہ احمد عباس سے بات کر سکتا ہوں۔‘‘ میں نے انگریزی ہی میں جواب دیا، ’’میں عباس ہی بول رہا ہوں۔ کہیے، کون صاحب بول رہے ہیں۔‘‘ دفعتاً فون کے دوسرے سرے پر انگریزی ہندوستانی میں بدل گئی مگر لہجہ ولایتی رہا۔ جیسے کوئی انگلستان سے پڑھ کر دس برس بعد حال ہی میں لوٹا ہو۔ ’’کیوں بھائی میری آواز پہچان سکتے ہو؟‘‘
میں تکلفاً جھوٹ بولا، ’’آواز تو آپ کی جانی بوجھی معلوم ہوتی ہے لیکن معاف کیجیےگا۔‘‘ اس نے میری بات کاٹ کر کہا بڑے بے تکلف انداز میں مگر لہجہ وہی ولایتی رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انگریزی فوج کا کرنیل ہندوستانی بول رہا ہو، ’’چھوڑو یار۔ تم میری آواز پورے پچیس برس بعد سن رہے ہو۔ آخری بار ہم لکھنؤ میں ملے تھے۔ انیس سو چھتیس میں۔‘‘ نہ جانے کیسے میرے دماغ میں ایک گھنٹی سی بجی۔ میں نے کہا، ’’برجیندر کمار سنگھ؟ برجو؟‘‘ ادھر سے آواز، ’’رائٹ برجو۔‘‘
’’برجو، میں نے خوشی سے چلا کر کہا۔۔۔ کہو بھئی اتنے دن کہاں رہے، کیا کرتے رہے؟ آج کل کیا کرتے ہو؟‘‘
ٹیلی فون پر بھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دوسری طرف جواب دینے سے پہلے اس نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی ہو۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز بالکل ہی بدلی ہوئی تھی۔ جیسے ایک دم کسی گہری فکر میں ڈوب گئی ہو، ’’یہ سب ایک لمبی کہانی ہے۔ کیا میں تم سے ابھی ملنے آ سکتا ہوں؟‘‘ میں نے کہا، ’’میں تو شہر سے بہت دور جوہو میں رہتا ہوں۔ مگر ہر روز دوپہر کو میں شہر آتا ہی ہوں۔ ایسا کیوں نہ کریں کسی ریستوران میں اکٹھے لنچ کھائیں۔ اب یہاں بمبئی میں بھی تمہارے لکھنؤ کی طرح ایک مے فیر (MAYFAIR) ریستوران کھل گیا ہے۔
’’مے فیر؟‘‘ اس نے ریستوران کا نام ایسے دہرایا جیسے دفعتاً کسی نے اس کی چٹکی لے لی ہو، ’’نہیں نہیں۔ میں تم سے کسی ریستوران میں نہیں ملنا چاہتا۔ وہاں بہت لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہم اطمینان سے باتیں نہیں کر سکیں گے۔‘‘
’’اچھا‘‘ میں نے کہا، ’’تو تم یہاں ہی آ جاؤ۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کتنے بجے آؤگے؟‘‘
’’جتنی دیر ٹیکسی کو چرچ گیٹ سے جوہو پہنچنے میں ٹائم لگے گا۔‘‘
’’کوئی چالیس پینتالیس منٹ میں اپنے برآمدے میں کھڑا ملوں گا۔‘‘
اگلے پینتالیس منٹ تک پچیس برس پرانی تصویریں میرے دماغ میں ابھرتی رہیں۔
برجو۔
برجیندر۔
برجیندر کمار سنگھ۔
کنور برجیندر کمار سنگھ۔
برجو۔
ہمارا یار برجو۔
برجو دی بریسنٹ۔
برجو جو خوبصورت تھا، قدآور تھا، ذہین تھا، ٹینس کا چمئپن تھا اور یونین میں بہترین مقرر تھا۔
برجو جس کے پیچھے درجنوں لڑکیاں دیوانی تھیں۔
ہائی کورٹ کے جج جسٹس سر رمیش سکسینہ کی بیٹی آشا سکسینہ جو آئی۔ ٹی۔ کالج میں پڑھتی تھی۔
ڈاکٹر ستیش بنرجی کی لڑکی کرونا جس کی خوبصورت آنکھیں جیمنی رائے کی کسی تصویر سے چرائی ہوئی لگتی تھیں۔
پروفیسر حامد علی کی چھوٹی بہن، ثریا ماجد علی جس نے کرامت حسین گرلز اسکول کا پردہ دار ماحول چھوڑ کر یونیورسٹی میں اسی سال داخلہ لیا تھا اور جو ہر ڈبیٹ اور ڈرامے میں یونین ہال میں سب سے آگے بیٹھتی تھی تاکہ برجو کو دل بھر کر دیکھ سکے۔
سرلا ماتھر جو ہندی میں ایم۔ اے کر رہی تھی اور کویتا لکھتی تھی اور جس کی ہر کویتا میں برجو کا روپ جھلکتا تھا۔
موہنا جسپال سنگھ جو نہایت خوبصورت تھی اور ایک چھوٹے موٹے جاگیردار کی بیٹی تھی اور جس نے صرف برجو کی وجہ سے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔
سلویا ٹامسن جو اسٹیشن ماسٹر کی لڑکی تھی اور ریلوے کلب کے ہر ڈانس میں برجو کو دعوت دینے خود اس کے ہاسٹل جاتی تھی۔ حالانکہ وہاں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع تھا۔
برجو۔۔۔
واقعی وہ کتنا قابل رشک نوجوان تھا۔
پہلی بار جب میری ملاقات اس سے ہوئی تو وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی آل انڈیا ڈبیٹ میں حصہ لینے لکھنؤ یونیورسٹی کی طرف سے آیا تھا۔
چھبیس برس بعد بھی مجھے اس سے وہ پہلی ملاقات اچھی طرح یاد تھی۔ میں اپنی یونیورسٹی یونین کی طرف آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے اسٹیشن گیا۔ اس ٹرین سے لکھنؤ، الہٰ آباد، بنارس، کان پور کے کالجوں کے ڈبیٹر آئے تھے۔ کل ملاکر وہ سب شاید بارہ یا چودہ تھے۔ لیکن ان سب میں ایک سب سے نمایاں تھا۔ نہ صرف اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ قدآور تھا اور بند گلے اور پوری آستینوں کے سوئٹر میں اس کا کسرتی بدن اپالو کے بت کی طرح گٹھا ہوا اور سڈول تھا بلکہ اس لیے بھی کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی اور جب میں نے اس سے ہاتھ ملایا تو اس کے شیک ہینڈ میں بڑا خلوص تھا اور گرم جوشی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہم لوگوں سے مل کر اسے واقعی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اسی ایک پل ہی میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم دونوں بڑے پرانے دوست ہوں۔ اور برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ پھر آل انڈیا ڈیبٹ ہوئی۔ موضوع زیر بحث یہ تھا کہ، ’’سماجی انقلاب کے بغیر سیاسی آزادی کافی نہیں ہے۔‘‘
میں اس موضوع کے خلاف بولا۔ اپنی تقریر میں میں نے سامراج کے خلاف اور قومی آزادی کی تحریک کی حمایت میں نہایت جذباتی تقریر کی اور ان لوگوں کو خوب لتاڑا جو جنگ آزادی کی قربانیوں اور خطروں سے بچنے کے لیے سماج سدھار کے گوشۂ عافیت میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ میری تقریر ختم ہوئی تو خوب زور کی تالیاں بجیں اور میں نے یہی سمجھا کہ میں نے میدان مار لیا ہے۔
میرے بعد لکھنؤ یونیورسٹی کے برجیندر کمار سنگھ کا نام پکارا گیا۔ اب وہ سفید فلالین کی پتلون پر بند گلے کا سیاہ جودھپوری کوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لباس میں وہ بڑا ہی جچ رہا تھا۔ ابھی اس نے تقریر شروع نہیں کی تھی کہ اوپر گیلری میں جہاں چکوں کے پیچھے گرلز کالج کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، دلچسپی کی ایک سرسراہٹ سی دوڑ گئی اور چکوں کے بیچ میں سے سیاہ خوبصورت آنکھیں اور رنگین آنچل جھلملانے لگے۔
’’مسٹر پریذیڈنٹ‘‘ اس نے نہایت شستہ انگریزی لہجہ میں تقریر شروع کی۔ مجھ سے پہلے میرے دوست نے جب اپنی تقریر ختم کی تو سب نے پرجوش تالیاں بجائیں۔ میں نے بھی تالیاں بجائیں۔ وہ تقریر واقعی لاجواب تھی۔ میرے خیال میں بہترین تقریر کے لیے انعام میرے اس دوست ہی کو ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ اتنے کمزور دلائل کو اتنی خوبصورتی اور اتنے زور و شور سے پیش کرنا واقعی بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ فیصلہ کرسکوں کہ وہ واقعی میری تعریف کر رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مسکراکر کہا، ’’مجھے یقین ہے کہ میرے دوست ایک بہت کامیاب وکیل ثابت ہوں گے۔۔۔‘‘ اور اس پر سارے ہال میں اتنے زور کا قہقہہ پڑا کہ اس کی لہروں میں میرے تمام زوردار دلائل بہہ گیے۔
اسے ڈیبیٹ میں اول انعام ملا۔۔۔ مجھے دوسرا۔۔۔ وہ تین دن علی گڑھ ٹھہرا۔ پہلے دن وہ مسٹر برجیندر کمار سنگھ تھا۔ دوسرے دن صرف ’’برجو‘‘ رہ گیا۔ جب دلوں اور دماغوں کی ہم آہنگی ہو تو غیریت کے فاصلے کتنی جلدی دور ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن پر جب میں اسے چھوڑنے گیا تو میں نے اس سے پوچھا تھا، ’’برجو یہ بات کہ سماجی انقلاب سیاسی آزادی سے زیادہ ضروری ہے۔ تم نے ایسی ہی ڈبیٹ کی خاطر اتنے زور و شور سے کہی یا تم واقعی اس میں اعتقاد رکھتے ہو؟‘‘
پچیس چھبیس برس کے بعد بھی اس کا جواب میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، ’’سنو! ملکوں اور قوموں کی آزادی ضروری ہے لیکن اتنی مشکل نہیں۔ سماجی انقلاب جو ہمارے دماغوں کو صدیوں کے تعصبات اور وہموں سے آزاد کرے وہ مشکل کام ہے، اور جب تک ہمارے دماغ آزاد نہیں ہوں گے ہمارے ملک کی سیاسی آزادی غیرمکمل رہےگی۔‘‘
پھر اس نے اور بڑی پتے کی باتیں کہی تھیں، ’’فرض کرو ہندوستان آزاد ہوگیا اور ہمارے تمہارے دماغ مذہبی جنون اور فرقہ وارانہ تعصب اور نفرت کے بندھنوں سے آزاد نہ ہوئے تو ذرا سوچو کیا ہوگا۔ اتنے برسوں کی تعلیم اور سماج سدھار کی باتیں کرنے کے بعد بھی ہم پڑھے لکھے ہندوؤں میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے ذہنوں کو پوری طرح ذات پات کے بندھنوں سے آزاد کر لیا ہے؟ تم مسلمانوں میں کتنے ہیں جو سچ مچ شیخ، مغل، پٹھان، جلاہے، کمہار کو برابر سمجھتے ہیں؟‘‘
میں نے اس سے پوچھا تھا، ’’اور برجو تم۔۔۔؟ کیا تمہارا دل اور دماغ ان بندھنوں سے آزاد ہے؟ کیا تم بڑے خاندان کے راجپوت ہوکر ایک اچھوت لڑکی سے بیاہ کر سکتے ہو؟ یا کسی طوائف زادی کو اپنی پتنی بنا سکتے ہو؟‘‘ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، ’’اگر مجھے اس سے محبت ہو تو ضرور کر سکتا ہوں۔ اور وقت آیا تو کرکے دکھا دوں گا۔‘‘ اور پھر اس کی ٹرین آ گئی اور وہ لکھنؤ واپس چلا گیا۔
اس کے بعد ہم ایک اور آل انڈیا ڈبیٹ کے سلسلے میں بنارس میں ملے تھے۔ اور سارناتھ کے کھنڈروں میں ساتھ گھومے تھے اور برجو نے مجھے مہاتما بدھ کے حالاتِ زندگی سنائے تھے اور کہا تھا، ’’اگر دھرم اور مذہب کے خیال ہی سے میں بیزار نہ ہو گیا ہوتا تو ضرور بدھ مت اختیار کر لیتا۔۔۔‘‘
’’جانتے ہو مہاتما بدھ کا دیہانت کیسے ہوا؟‘‘ اس نے میوزیم میں مہاتما بدھ کی شانت اور مسکراتی ہوئی مورتی کے سامنے کھڑے ہوئے مجھ سے کہا تھا، ’’وہ ایک غریب اچھوت کے ہاں بھیک مانگنے گیے اور اس بیچارے کے پاس گھر میں صرف سڑا ہوا سور کا گوشت تھا۔ وہی اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ گوشت سڑکر زہریلا ہو چکا تھا انہوں نے اسے کھا لیا۔ جان دے دی مگر کسی غریب اچھوت کا دل نہیں توڑا۔۔۔‘‘
پھر جب ہم یہی باتیں سوچتے ہوئے تانگے میں شہر واپس ہو رہے تھے، ہم نے دیواروں پر دیوداس فلم کے اشتہار لگے دیکھے تھے اور برجو نے کہا تھا، ’’اور ایک بھائی دیوداس تھے کہ پاروتی کو تو منجدھار میں چھوڑا ہی تھا چندرال کا دل بھی تور دیا۔ اور شراب کے سمندر میں ڈوب گیے۔ مگر سماج نے انسانوں کے درمیان جو کھائیاں کھود رکھی ہیں ان کو پار نہ کر سکے۔‘‘
میں نے کہا تھا، ’’دیوداس کوئی فرضی فلمی ہیرو نہیں تھا۔ شرت بابو نے ایک معمولی انسان کا کردار دکھایا ہے جو سماج کے مقابلے میں ہماری تمہاری طرح کمزور تھا۔‘‘ اور اس نے ہنس کر کہا تھا، ’’تمہاری طرح کمزور ہوگا۔ اگر یہ صورتِ حال مجھے پیش آئی تو میں کمزور ثابت نہیں ہوں گا۔۔۔‘‘
اس رات ہم لوگ بنارس سے رخصت ہو رہے تھے لیکن ہماری ٹرینیں آدھی رات کے بعد روانہ ہونے والی تھیں۔ میری ٹرین ڈیڑھ بجے اور برجو کی ٹرین پونے تین بجے۔ ڈبیٹ کے لیے اور جتنے طالب علم مختلف یونیورسٹیوں سے آئے تھے وہ سب جا چکے تھے۔ صرف میں اور برجو رہ گیے تھے اور ہماری دیکھ بھال کرنے کے لیے بنارس یونیورسٹی کا ایک ایم اے کا طالب علم تھا گوند سکسینہ۔ کھانے کے بعد ہم باتیں کر رہے تھے کہ گوند نے کہا، ’’ریل میں تو ابھی کئی گھنٹے ہیں چلیے آپ لوگوں کو گانا سنوا دیں۔۔۔‘‘
میں نے اس وقت تک بھی کسی طوائف کا گانا نہیں سنا تھا، مگر بنارس کی گانے والیوں کی بڑی تعریف سنی تھی کہ پکے گانے، دادرا اور ٹھمری میں ان کا جواب نہیں۔ سو میں نے کہا ’’یہ اچھا خیال ہے چلو برجو۔۔۔‘‘ مگر اس نے کہا، ’’چھوڑو جی، اچھے خاصے یہاں گپ شپ کر رہے ہیں وہاں کوئی کالی موٹی بھدی بائی جی پان کھا کھاکے پکا گانا سنائیں گی اور ہمیں بور کریں گی۔۔۔‘‘ اس پر گوند بولا، ’’تم لکھنؤ والے سمجھتے ہو کہ لکھنؤ کے چوک کے باہر حسن کہیں ہے ہی نہیں۔۔۔ ارے ایک بار لکشمی کو دیکھ بھی لوگے تو نہ جانے لکھنؤ کی کتنی ریلیں نکل جائیں گی۔‘‘
مگر برجو نہیں مانا۔ تمہاری لکشمی بائی تم بنارس والوں کو مبارک۔۔۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کوٹھے والیو ں کا گانا سننے میں اپنے کو کوئی دلچسپی نہیں۔‘‘ اور مجھے کہنے کا موقع مل گیا، ’’کیوں سماج سدھارک جی ویشیا کے گھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیا۔۔۔؟‘‘ برجو کو کہنا ہی پڑا، ’’ڈر تو مجھے شیطان کے گھر جاتے ہوئے بھی نہیں لگتا۔۔۔‘‘ اور سو ہم لوگ تانگہ لے کر لکشمی کے کوٹھے کے لیے روانہ ہو گیے۔
اتنے برسوں کے بعد بھی لکشمی کی صورت کو میں نہ بھولا تھا۔ چھوٹا سا بوٹا سا قد، گدرایا ہوا جسم، گوری تو نہیں مگر سنہری رنگت، گھنے لمبے بال جن کو دوچوٹیوں میں گوندھا ہوا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں اور بوجھل لمبی پلکیں۔ لالی رنگے ہونٹ جن پر ایک عجیب سی اداس سی مسکراہٹ سی کھیل رہی تھی۔ چھوٹی سی مگر بڑی خوبصورت سی ناک جس میں ہیرا جڑی ایک چھوٹی سی نتھنی پڑی ہوئی تھی۔ گوند نے میرے کان میں کہا، ’’اس نتھنی کو اتارنے کے لیے ایک جاگیردار صاحب پچاس ہزار تک پیش کر چکے ہیں۔۔۔‘‘
مجرا شروع ہوا۔ ہمیں ماننا پڑا لکشمی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی سریلی اس کی آواز ہے۔ ٹھمری کے بعد دادرا اور دادرا کے بعد غزل۔۔۔ گوند کی فرمائش پر ایک آدھ فلمی گیت بھی ہوا۔ محفل میں کتنے ہی لوگ تھے جو بھوکی نظروں سے لکشمی کو گھور رہے تھے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ خود لکشمی کی نگاہیں برجو کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں۔ آہستہ آہستہ محفل بکھرتی گئی۔ اپنی اپنی جیبیں خالی کرکے لوگ اٹھتے گیے۔ پھر صرف ہم لوگ رہ گیے۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ ساڑھے بارہ بج رہے تھے۔ میں نے کہا، ’’میری گاڑی کا تو وقت ہو گیا۔ چلو بھئی گوند۔۔۔‘‘
گوند میرے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن جب برجو نے اٹھنا چاہا تو لکشمی نے اپنا مہندی لگا چھوٹا سا نرم ہاتھ اس کے سخت ٹینس کھیلنے والے ہاتھ پر رکھ دیا، ’’آپ کو ہماری قسم کنور صاحب لکھنؤ کی گاڑی میں تو ابھی بہت دیر ہے۔۔۔‘‘ برجو نے حیران ہوکر پہلے میری طرف دیکھا پھر گوند کی طرف۔ اور پھر لکشمی کی طرف جس کا ہاتھ اب تک اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھنا بھی چاہتا ہے اور لکشمی کو مایوس کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے انگریزی میں کہا۔ شام کی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے THIS MEAT IS POISOND ’’اس گوشت میں زہر ہے۔‘‘
برجو نے بھی انگریزی میں جواب دیا، ’’جانتا ہوں۔ مگر کسی کا دل دکھانے سے زہر کھالینا بہتر ہے۔‘‘
’’چلو گوند ہم چلتے ہیں۔‘‘ میں نے کسی قدر چڑ کر کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ایک عزیز دوست ایک گندی نالی میں گرپڑا ہے اور وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا۔
’’اچھا تو پھر اگلے سال لکھنؤ کی ڈبیٹ میں ملیں گے۔‘‘ برجو نے مجھ سے صلح کرنے کے لیے آواز دی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ برجو کا جو خیالی مجسمہ میں نے اپنے من میں بنایا تھا اس لمحے میں وہ چکناچور ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سماجی انقلاب پر تقریر کرنے والا برجو، مہاتما بدھ کے پوتر مارگ پر چلنے والا برجو ایک معمولی رنڈی باز نکلےگا۔ غصے سے بھرا میں زینے سے اتر ہی رہا تھا کہ آواز آئی ’’سنیے‘‘ مڑکر دیکھا تو لکشمی تھی۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور اس کے لبوں کے کنارے کانپ رہے تھے، ’’میں نے آپ کے دوست کو روک لیا۔‘‘ وہ بولی، ’’اس کے لیے میں آپ سے شما مانگتی ہوں۔‘‘ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور مڑکر جانے لگا۔ اس پر اس کی آواز میں تیر کی سی تیزی تھی، ’’جانے سے پہلے یہ سنتے جائیے کہ میں انگریزی سمجھتی ہوں اگر میں زہریلا گوشت ہوں تو کبھی یہ بھی سوچیےگا کہ میرے جیون میں یہ بِس کس نے گھولا ہے۔‘‘ میں کوئی جواب نہ دے سکا اور وہاں سے چلا آیا۔
اگلے برس جب میں لکھنؤ آل انڈیا ڈبیٹ کے لیے گیا تو میں اس واقعہ کو تقریباً بھول چکا تھا۔ یونیورسٹی کے طالب علموں کا کسی طوائف کے کوٹھے پر گانا سننے جانا یا وہاں رات بھر کے لیے بھی ٹھہر جانا کوئی ایسا غیرمعمولی سانحہ نہیں کہ اس پر برسوں سوچ بچار کی جائے۔ برجو کا رویہ اس وقت مجھے ضرور برا لگا تھا۔ مگر بعد میں میں نے یہ سوچ کر اسے معاف کر دیا تھا کہ جوانی میں ایک آدھ بار کس کے پیر نہیں لڑکھڑاتے۔ وہ اسٹیشن پر مجھے لینے آیا تھا اور اگلے تین دن تک تقریباً وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی رہا۔ وہ بی اے فرسٹ ڈویژن میں پاس کر چکا تھا اور اب ایم اے میں پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ’’میرے ماں باپ تو چاہتے ہیں میں آئی، سی، ایس کے مقابلے میں شریک ہوں۔ لیکن میں سرکاری نوکری کرنا نہیں چاہتا۔‘‘
میں نے پوچھا، ’’تب کیا کروگے؟‘‘ بولا، ’’ایم اے کرکے کسی چھوٹے موٹے کالج میں لیکچرر ہوجاؤں گا۔ یا ایل ایل بی کرکے وکالت کروں گا۔ ورنہ تمہاری طرح میں بھی جرنلزم کے میدان میں آکو دوں گا۔‘‘ اس نے مجھے پورے لکھنؤ کی سیر کرائی۔ اور اس بار مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکیوں میں کتنا مقبول ہے۔ ہم یونیورسٹی یونین کے کیفے میں چائے پی رہے تھے کہ کرونا بنرجی مل گئی اور کہنے لگی، ’’دیکھو مسٹر برجیندر کو مارا مارے بنگالی کالج کے پروگرام میں زرور آنا۔ ہم گرودیو کا ناٹک رکتوکروبی کر رہے ہیں۔‘‘ اور جب برجو نے کہا، ’’کرونا میرا آنا تو مشکل ہے۔ یہ میرے دوست علی گڑھ سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کو لکھنؤ کی سیر کرا رہا ہوں‘‘ تو وہ بولی، ’’تو اپنے فرینڈ کو بھی لے آئیے نا پلیز۔‘‘ اور اس کی جیمنی رائے کی تصویر جیسی بنگالی آنکھوں میں پیار ہی پیار بھرا ہوا تھا۔
وہاں سے مجھے وہ لائبریری دکھانے لے گیا تو سرلا ماتھر سے ملاقات ہو گئی جو برجو کو کوی سمیلن میں مدعو کرنے کے لیے تلاش کر رہی تھی۔ وہ بولی ’’برجیندر جی! یہ میں نے ایک نئی کویتا لکھی ہے۔ اسے پڑھ کر بتائیےگا کیسی ہے، میں کوی سمیلن میں بھی پڑھنے والی ہوں۔‘‘ جب وہ چلی گئی تو برجو نے کویتا مجھے دکھائی۔ عنوان تھا، ’’میرے سپنے‘‘ اور دو ہی سطریں سن کر میں جان گیا کہ اس بیچاری کے سارے سپنوں کا مرکز برجو ہی تھا۔ شام کو ٹینس کلب میں آشا سکسینہ سے ملاقات ہوئی جن کا اصرار تھا کہ برجو ٹینس ٹورنامنٹ میں مکسڈ ڈبلز کے لیے ان کا پارٹنز بن جائے اور جس انداز سے وہ اسے ’’پارٹنر پارٹنر‘‘ کہہ کر بلا رہی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں برجو کو زندگی بھر کا ’’پارٹنر‘‘ بنانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔
مے فیر ریستوران میں چائے پینے گیے تو وہاں ایک نہایت خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی ’’ہیلو برجو‘‘ کہہ کر دوڑی اور جب برجو نے اس کا تعارف کرایا تو معلوم ہوا وہ ہے موہنا جسپال سنگھ۔ میں نے دیکھا اس کی کاجل لگی آنکھوں میں برجو کو دیکھتے ہی ایک عجیب سی آگ چمک اٹھی ہے اور نہ جانے کیوں مجھے ان بھوکی، سلگتی ہوئی آنکھوں سے ڈر سا لگا۔ اگلے دن میں نے برجو سے پوچھا، ’’ارے یار تم بڑے خوش قسمت ہو کہ یہ سب لڑکیاں تم پر مرتی ہیں۔ مگر اب تک یہ نہ پتہ چلا کہ تم کس سے دلچسپی لیتے ہو۔ یا سب سے ہی فلرٹ کرتے ہو؟‘‘
وہ بولا، ’’میں جس میں دلچسپی لیتا ہوں وہ کوئی اور ہے اور اس سے میں بہت جلد شادی کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا، ’’اگر ان سب حسین اور اسمارٹ لڑکیوں کو چھوڑ کر تم نے کوئی اور پسند کی ہے تو وہ واقعی کوئی خاص چیز ہوگی۔ ہمیں بھی ملاؤ۔‘‘ اس نے مسکراکر کہا تھا، ’’خاص چیز تو ہے وہ۔ اسی لیے میں نے اسے پردے میں رکھ چھوڑا ہے۔‘‘ میں نے کہا، ’’ہم مسافروں سے کیا پردہ۔ ہم تمہارے رقیب نہیں ہیں یار۔‘‘
’’تو پھر آج شام کو چار بجے مے فیر ریستوران میں چائے پیو اور اس سے ملو۔‘‘
’’کون۔ موہنا؟‘‘
نہیں موہنا تو بور ہے۔ اگرچہ میرے ماتا پتا اس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک جاگیردار کی بیٹی ہے لیکن جس سے میں تمہیں ملانا چاہتا ہوں وہ کوئی اور ہی ہے۔‘‘
چار بجے مے فیر میں داخل ہوا تو ایک کونے کی میز پر برجو کے پاس سفید ساڑی میں ملبوس ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ میں بالکل قریب پہنچ گیا تب بھی اس کی صورت نہ دیکھ سکا۔
’’تم ان سے مل چکی ہو؟‘‘ برجو نے کہا اور سفید ساڑی والی لڑکی نے مڑ کر مجھے دیکھا۔
وہ لکشمی تھی!
’’نمستے!‘‘ اس نے آنکھیں جھکاکر کہا۔
’’نمستے!‘‘ میں نے نہایت بد دلی سے جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ کر بینڈ کی دھن سننے لگا۔ اس شام کو گومتی کے کنارے گھومتے ہوئے گھنٹوں میں اور برجو اس مسئلے پر باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا، ’’برجو تم پاگل ہوگیے ہو کہ موہنا جسپال سنگھ اور آشا سکسینہ اور کرونا بنرجی اور سرلا ماتھر جیسی خوبصورت پڑھی لکھی بڑے خاندانوں کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اس طوائف سے شادی کر رہے ہو۔‘‘
’’لکشمی طوائف نہیں!‘‘ اس نے غصے سے کہا۔
’’طوائف نہ سہی طوائف زادی سہی، مگر تم نے اس میں کیا دیکھا ہے جو ساری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اسے پسند کیا ہے؟‘‘
’’وجہ تو ایک ہی ہے، میرے دوست۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ میری خاطر اپنے گھر والوں کو، اپنے پیشے کو، ماضی کو چھوڑ کر چلی آئی ہے۔ اگلے مہینے ہم شادی کرنے والے ہیں۔‘‘
’’اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے گھر والے تمہیں اس حماقت کی اجازت دے دیں گے؟‘‘
’’مجھے ان کی اجازت نہیں چاہیے۔ زندگی کے ایسے فیصلوں کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ ماں باپ کی بھی نہیں، دوستوں کی بھی نہیں۔‘‘
’’شکریہ‘‘ میں نے بڑی تلخی سے کہا تھا، ’’تو پھر مجھے یہ سب کیوں سنا رہے ہو؟‘‘
چلتے چلتے رک کر اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، ’’تمہاری اجازت نہیں چاہیے، تمہاری محبت چاہیے۔ دوست جج بن کر اپنے دوستوں کے اعمال کی جانچ پڑتال نہیں کرتے، ان کو اپنی دوستی اور محبت کی چھاؤں میں پناہ دیتے ہیں۔‘‘ اس کے بعد میرا کچھ کہنا بےکار تھا۔ میں نے صرف اتنا پوچھاتھا، ’’تو اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟‘‘
اس نے کہا تھا، ’’کل میں اپنے وطن جارہا ہوں۔ اپنے ماں باپ کو اس فیصلے کی اطلاع دینے۔ ماتا جی بیمار ہیں اس لیے خط لکھ کر ان کو ایک دم SHOCK دینے کے بجائے خود جاکر انھیں زبانی سمجھانا چاہتا ہوں۔‘‘
’’اور اگر وہ لوگ راضی نہ ہوئے تو؟‘‘
’’تو ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر یہ شادی ہوگی۔‘‘ اور اس کے کہنے کے انداز میں اتنی قطعیت تھی کہ میں خاموش ہو گیا۔ اگلے دن ہم اکٹھے ہی اسٹیشن پر گیے۔ پہلے اس کی گاڑی جاتی تھی اس کے بعد میری۔ ٹکٹ کھڑکی پر جاکر جب اس نے کہا، ’’ایک فرسٹ کلاس شام نگر‘‘ تو بابو نے پوچھا، ’’سنگل یا ریٹرن؟‘‘
’’ریٹرن‘‘ اس نے بڑے زور سے کہا۔ ’’ہمیشہ واپسی کا ٹکٹ ہی لینا چاہیے۔‘‘
لکشمی بھی اسے چھوڑنے اسٹیشن پر آئی تھی۔ جب گارڈ نے سیٹی دی اور جھنڈی ہلائی اور برجو اپنے کمپارٹمنٹ میں سوار ہوا تو لکشمی کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔
’’اری پگلی۔ گھبراؤ نہیں۔‘‘ برجو نے چلتے چلتے چلاکر کہا، ’’میں تو پرسوں ہی لوٹ آؤں گا۔ یہ دیکھ تین دن کا ریٹرن ٹکٹ۔‘‘
ریل چل پڑی تھی اور ریل میں برجو تھا۔ برجو کے ہاتھ میں ایک ہرا واپسی کا ٹکٹ تھا۔ پھر ریل آگے جاکے اپنے دھوئیں کے بادل میں کھو گئی۔ اور اب نہ ریل تھی نہ برجو اور نہ وہ واپسی کا ٹکٹ اور اب پلیٹ فارم پر صرف لکشمی تھی۔ لکشمی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان آنسوؤں میں پریتم سے بچھڑنے کا غم بھی تھااور اس سے جلد پھر ملنے کی آرزو اور امید بھی تھی۔
میں علی گڑھ واپس چلا آیا۔ امتحان کی تیاریوں میں لگ گیا۔ چند ہفتے میں نے برجو کے خط کا انتظار کیا مگر کوئی خط نہ آیا۔ میں نے سوچا نئی نئی شادی ہوئی ہے شاید ہنی مون پر کہیں گیے ہوں۔ پھر امتحان کے چکر میں سب کچھ بھلانا پڑا۔ امتحان ختم ہوا تو مجھے نوکری کے سلسلے میں بمبئی آنا پڑا۔ نئے نئے کام کا ایساچکر پڑا کہ علی گڑھ، لکھنؤ، برجو، لکشمی سب پرانی یادیں بن کر کھو گیے۔ ۴۳ء کا سیاسی ہنگامہ آیا۔ ۴۶ء میں فساد اور خون خرابے ہوئے۔ ۴۷ء میں آزادی آئی۔ میں کئی بار دنیاکے سفر کو گیا۔ زندگی میں کتنی ہی خوشیاں اور کتنے ہی غم آئے اور بگولوں کی طرح گزر گیے۔ کتنی ہی کامیابیوں اور ان سے بھی زیادہ پریشانیوں اور ناکامیوں سے دوچارہونا پڑا پھر بھی برجو اور لکشمی کی یاد ایک سوالیہ نشان بن کر میرے دل کے ایک کونے میں دبکی رہی اور اس صبح جب ٹیلیفون کی گھنٹی بجی، وہ سوالیہ نشان دن دہاڑے ایک بھوت بن کر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔
اس بار گھنٹی بجی تو وہ ٹیلیفون کی نہیں تھی، دروازے کی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ایک ڈھیلی سی ملگجی سی بش شرٹ اور پتلون پہنے ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا موٹے موٹے شیشوں کے عینک سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا پورٹ فولیو تھا، جیسا انشورنس ایجنٹ رکھتے ہیں۔ عین اسی وقت جب میں اور برجو جو پچیس برس بعد ملنے والے تھے یہ بوڑھا انشورنس ایجنٹ نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا۔
’’کیا چاہیے؟‘‘ میں نے قدرے درشتی سے پوچھا۔ جھریوں دار گہرے سانولے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، ’’کیوں بھول گئے؟‘‘
’’برجو! اگلے لمحے ہم دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے۔
’’میں بہت بدل گیا ہوں گا؟‘‘ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، ’’تم نے بھی نہیں پہچانا۔‘‘
یہ واقعہ تھا کہ پچیس برس پہلے کے برجو اور اس بوڑھے میں کوئی دور کی بھی مشابہت نہ تھی۔ میں نے سوچا ضرور بے چارہ سخت بیمار رہا ہوگا۔ تبھی تو اس کے چہرے اور بازوؤں پر کھال اس طرح لٹکی ہوئی ہے جیسے اس کے ڈھیلے کپڑے۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پچیس برس میں ہم سب ہی بدل گیے ہیں۔ مجھے ہی دیکھو چندیا بالکل صاف ہو گئی ہے۔
اس نے کہا، ’’میں نے تمہارا نام ٹیلیفون ڈائرکٹری میں تلاش کیا۔ امید تو نہ تھی تم ملوگے۔ سنا ہے اکثر ہندوستان سے باہر رہتے ہو۔‘‘ ٹیلیفون کے ذکر پر میں نے کہا، ’’میں تو فون پر تمہاری آواز سن کر سمجھا تھا کوئی انگریز یا امریکن ہے جس سے میں کہیں سفر میں ملا ہوں گا۔‘‘
’’اور میرا ACCENT؟ میں بھی تو کتنے ہی برس انگلستان میں رہا ہوں۔ ویسے ہی بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔‘‘ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے اور اسی بات کو چھپانا بھی چاہتا ہے۔ کئی قسم کے خیالات اور خدشے میرے دماغ میں آئے۔ شاید اس کی نوکری چھٹ گئی ہے۔ بیکار ہے۔ شاید مدد مانگنے آیا ہے۔ شاید اس کو شراب کی لت پڑ گئی ہے تب ہی بہکا بہکا سا لگتا ہے اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپتی ہیں شاید اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ اس لیے اس کی آنکھیں بےچینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں۔ کچھ سیکنڈ تک ہم دونوں ایک دوسرے کے چہرے میں اپنے ماضی کی تلاش کرتے رہے۔ پھر میں نے کہا، ’’کیوں بمبئی اکیلے ہی آئے ہو۔ بھابی ساتھ نہیں ہیں کیا؟‘‘ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا، ’’میں نے طلاق لے لی ہے۔‘‘
لیکن اب کم سے کم اس کی پریشانی کی وجہ تو معلوم ہو گئی۔ اتنے برسوں کے شدید عشق کے بعد اگر طلاق کی نوبت آئی ہے تو اس حالت پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ’’بڑا افسوس ہے برجو، لیکن ہوا کیا جو طلاق لینی پڑی؟ اس عمر میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔‘‘
’’میاں بیوی!‘‘ اس نے دونوں لفظوں کو کسی کڑوی دوا کی طرح تھوکا۔ پہلے دن ہی سے ہماری شادی ایک جھوٹ تھی۔ ایک بھیانک غلطی تھی۔ چوبیس برس تک میں نے اس غلطی سے نباہ کیا۔ اس جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہوا۔‘‘
میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں اس لیے میں خاموش رہا۔ میرے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی وہ بے چارہ مجھ سے کوئی صلاح مشورہ کرنے کے لیے نہیں اپنے دل کا بخار نکالنے کے لیے آیا تھا۔ کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس نے ایک سگار جلایا اور منہ سے دھوئیں کا ایک بادل اڑاتا ہوا بولا تم سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنے برس کہاں غائب رہا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میں بیوی کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر انگلستان چلا گیا۔ آئی سی ایس کا امتحان دیا اور بدقسمتی سے پاس ہو گیا۔
’’تو تم آئی سی ایس میں تھے اور ہمیں کبھی پتہ ہی نہ چلا؟‘‘
’’میں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تم لوگ ان دنوں سرکاری نوکریوں کابائیکاٹ کر رہے تھے۔ ستیاگرہ کرکے جیل جا رہے تھے۔ میں کس منہ سے تم لوگوں کے سامنے آتا۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر ایسے ایسے مقام چنے جہاں کسی پرانے دوست سے ملاقات نہ ہو۔ پہلے کئی سال فرینٹر میں رہا پھر آسام میں۔ پھر کورگ میں وہیں ہمارا پہلا لڑکا پیدا ہوا۔۔۔‘‘
کتنی ہی دیر وہ دھوئیں کے بادلوں میں نہ جانے کیسی کیسی تصویریں بناتا اور بگاڑتا رہا۔ پھر بولا، ’’مگر وہ لڑکا ہمارا نہیں تھا۔ وہ اس کا لڑکا تھا۔ جو میرے ایک چپراسی سے پیدا ہوا تھا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو تم سمجھ سکتے ہو کہ میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ چند مہینے تک تو میں بالکل پاگل ہو گیا۔ شراب تو میں پہلے بھی پیتا تھا لیکن اب میں نے اپنی ذلت کو ڈبونے کے لیے اندھا دھند پینا شروع کر دیا۔ جب وہسکی سے کام نہ چلا تو کوکین کھانے لگا۔ تین مہینے پاگل خانے میں علاج کرایا۔ اور جب علاج کرکے حواس پر کسی قدر قابو پایا اور باہر نکلا تو نوکری سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ذلیل ہوکر نکالے جانے سے یہی بہتر تھا کہ میں خود ہی بیماری کا بہانہ کرکے وقت سے پہلے پنشن کی درخواست دے دوں۔ میں نے اس کی منت کی کہ مجھے طلاق دے دو اور بچہ لے جاؤ۔ میری ساری پنشن لے لو۔ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنی نئی زندگی بنا سکوں۔ لیکن وہ نہ مانی۔ بولی، ’’تم نے میری زندگی تباہ کی ہے اب تم مجھ سے اتنی آسانی سے چھٹکارا نہ پاؤگے۔‘‘
’’پھر؟‘‘ میں نے نرمی سے کہا۔
پھر میں ان دونوں کو لے کر انگلستان چلا گیا۔ ہندوستان میں اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھا۔ پنشن بیچ کر جتنا روپیہ وصول ہوا اس سے میں نے لندن میں مکان خرید لیا۔ ایک حصے میں ہم خود رہتے تھے اور باقی میں ہندوستانی اور افریقین طالب علم کرایہ دے کر رہتے تھے۔ بس یہی ہمارے گزارے کی صورت تھی۔‘‘
’’پھر؟‘‘
’’پھر وہی پرانی کہانی دہرائی جاتی رہی۔ اب مجھ میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ میں اس بدکارسے کچھ بازپرس بھی کر سکتا۔ رات کو جب تک ’’پیاؤ‘‘ بند نہ ہوتامیں وہاں بیٹھا شراب پیتا رہتا تھا اور وہ نوجوان طالب علم کرایہ داروں سے کرایہ وصول کرتی تھی۔ دس سال میں تین اور بچے ہو گیے۔ ایک بالکل کالا۔ ایک سانولا۔ ایک گورا۔‘‘
مجھے اپنے دوست کی حالت پر رحم بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ آخر مجھ سے نہ رہا گیا اور میں بول ہی پڑا۔ اور تم نامردوں کی طرح سب دیکھتے رہے۔ اور تم سے یہ نہ ہوا کہ دو جوتے رسید کرتے اور نکال باہر کرتے اس چھنال کو۔ میں نے چوبیس برس ہوئے تم سے کہا تھا۔ برجو، رنڈی کی بیٹی سے سوائے بے وفائی کے تم اور کچھ نہ پاؤگے۔
’’رنڈی کی بیٹی؟‘‘ اس نے حیرت سے دہرایا۔
’’ہاں ہاں رنڈی کی بیٹی لکشمی!‘‘ میں نے نفرت سے بھرپور لہجے میں وہ نام لے ہی ڈالا جو اتنی دیر سے ہم دونوں کے درمیان ایک پہیلی بنا ہوا تھا جس کو بوجھنے کی ہمت نہ مجھ میں تھی نہ اس میں۔
’’لکشمی؟‘‘ اس نے ایسے لہجے میں دہرایا جیسے عمر میں پہلی بار یہ نام سنا ہو۔ پھر وہ بے اختیار ہنس پڑا اور ہنستا رہا، ہنستا رہا۔ ایک قہقہے کے بعد دوسرا قہقہہ، اسے ہنسی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ لیکن اس ہنسی میں ایک کھوکھلی سی آواز تھی، کوئی مسرت نہ تھی۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہا۔
’’تو تم سمجھ رہے ہو کہ میں اب تک تم سے لکشمی کا ذکر کر رہا ہوں؟‘‘
’’تو اور کیا؟‘‘ میں نے کہا، ’’اسی سے تو تم نے شادی کی تھی نا؟‘‘
’’کاش ایسا ہی کیا ہوتا دوست‘‘ اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سی سانس بھر کر کہا، ’’مگر جس سے میری شادی ہوئی وہ طوائف کی بیٹی لکشمی نہیں تھی۔۔۔ ایک جاگیردار کی بیٹی موہنا تھی۔‘‘
موہنا۔ اور میں نے اس حسین چہرے کو یاد کرنے کی کوشش میں جو میں نے لکھنؤ کے مے فیر ریستوران میں دیکھا تھا اور پچیس برس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ کاجل کا حاشیہ لگی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب آگ چمک رہی تھی۔ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن اسی آگ میں برجو کی زندگی جھلس جائےگی اور لکشمی؟ میں نے پوچھا، ’’لکشمی کا کیا ہوا؟ آخری بار جب ہم لکھنؤ میں ملے تھے مجھے یاد پڑتا ہے تم تین دن کا واپسی کا ٹکٹ لے کر اپنے گھر جا رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کو اس شادی کی اطلاع دینے؟‘‘
جواب میں اس نے کچھ نہ کہا۔ جیب سے ایک پرانا بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ۔ اس کاغذ کی تہوں میں سے ایک ریلوے ٹکٹ کا آدھا حصہ نکلا جو برسوں کے بعد اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ اس پر چھپے ہوئے سب حرف غائب ہوگیے تھے۔ صرف اس کے سائز سے معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ ریٹرن ٹکٹ کا واپسی والا آدھا حصہ رہا ہوگا۔
اب میں کچھ کچھ سمجھا کہ کیا ہوا ہوگا۔
’’تو جب تم گھر پہنچے تو کنور صاحب اور کنور رانی کو قائل نہ کر سکے؟ تمہارے ماتا پتا نے تمہیں جائیداد سے عاق کرنے کی دھمکی دی؟‘‘ اس نے سر ہلاکر اقرار کیا کہ ایسا ہی ہوا تھا۔
’’انہوں نے تمہیں لکھنؤ واپس جانے سے بھی روک دیا؟‘‘ اس کے سر کی جنبش نے اثبات میں جواب دیا۔
’’انہوں نے زبردستی تمہاری شادی اپنے جاگیردار دوست کی بیٹی موہنا سے طے کر دی؟ انہوں نے تمہیں انگلستان بھیجنے کا لالچ دیا۔ انہوں نے تمہیں ڈرایا کہ اگر تم نے طوائف کی بیٹی سے شادی کرکے سماج میں طوفان برپا کیا تو تمہیں نہ صرف آئی سی ایس سے ہاتھ دھونا پڑے گا بلکہ کوئی بھی معقول نوکری نہ مل سکےگی۔‘‘
’’اپنی اسی کمزوری کا خمیازہ آج تک میں بھگت رہاہوں۔ میں جو دیوداس کی کمزوری پر ہنستا تھا!‘‘ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایسی باتیں کرکے اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا ہے۔
’’اور سنو ریٹرن ٹکٹ کی تین دن کی مدت گزر گئی اور تم لکھنؤ واپس نہ آئے اور واپسی کا حصہ بےکار تمہاری جیب میں پڑا رہا؟‘‘
’’یہی تو مشکل ہے، میرے دوست۔‘‘ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ زندگی کے سفر میں ریٹرن ٹکٹ نہیں ملتا۔ جہاں سے ہم چلے ہیں اور جن مقاموں سے گزرے ہیں ہزار کوشش کرنے پر بھی ہم وہاں لوٹ کر نہیں جا سکتے۔‘‘
’’تو اب کیا ارادہ ہے؟‘‘ میں نے کافی دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ برجو نے کہا، ’’میں نے موہنا کو لندن کا گھر دے دیا ہے۔ اپنی ساری جائیداد اس کے نام لکھ دی ہے۔ اس قیمت پر وہ مجھے طلاق دینے پر راضی ہوئی ہے۔‘‘
’’تو کیا وہ۔۔۔ موہنا۔۔۔ ہمیشہ سے ایسی تھی؟‘‘
’’نہیں۔ تب ہی تو پچیس برس نباہ کرنے کی کوشش کی میں نے۔‘‘
’’پھر ایسی کیسے ہوگئی؟
کچھ دیر تک برجو خاموش رہا۔ اس نے نیا سگار جلایا، ’’آہستہ آہستہ اس نے کئی کش لیے۔ پھر وہ بولا، ’’گناہگار تو میں ہی ہوں۔ میں اسے وہ کچھ نہ دے سکا جسے وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ کوشش کرنے کے باوجود میں اس سے محبت نہ کر سکا۔‘‘
’’تو کیا، اسے لکشمی کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا؟‘‘
’’شادی کے سال بھر بعد معلوم ہو گیا تھا۔ اس وقت میری پوسٹنگ فرینٹر میں تھی۔ ایک رات میں کلب سے بہت شراب پی کر لوٹا تھا۔ جب میں اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے گیا تو چاندنی میں دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے لکشمی میرے پلنگ پر لیٹی ہے۔ میں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بہت پیار کیا۔ اس نے کہا برجو تم رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ وعدہ کرو اب مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاؤگی۔ لکشمی لیکن وہ لکشمی نہیں تھی۔ اور اس رات کے بعد سے موہنا بھی وہ نہ رہی۔ کچھ اور ہی ہو گئی۔ اس نے میرے ساتھ شراب پینا شروع کی۔ پھر دوسروں کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تم کو معلوم ہی ہے۔ مگر میں اب بھی اس کو دوش نہیں دیتا۔ اپنی تباہی اور اس کی تباہی دونوں کا ذمہ دار میں ہوں۔‘‘
’’اور لکشمی؟‘‘
’’اس کی زندگی بھی میری وجہ سے تباہ ہو گئی۔ جب میرا سہارا چھٹ گیا تو اسے اپنی ماں کے پاس جانا پڑا۔ وہ سب کرنا پڑا جس سے صرف میں اسے بچا سکتا تھا۔ بنارس سے دہلی کے چاوڑی بازار میں آئی۔ وہاں سے کلکتہ کے سوناگاچی میں۔ وہاں سے بمبئی کے فارس روڈ پر۔ اب سنا ہے کہ وہ بوڑھی اور بیمار، اس دھندے کے لیے بےکار ہوکر بنارس لوٹ گئی ہے۔ وہاں کسی مندرکی سیڑھیوں پر پڑی ہے اور۔۔۔ اور۔۔۔؟‘‘
’’اور؟‘‘ میں نے پوچھا۔
’’میں اس کے پاس جارہا ہوں۔‘‘
اس شام کو جب میں اسے چھوڑنے سٹیشن پر گیا اور ہم ٹکٹ خریدنے لگے تو بابو نے حسب معمول پوچھا ’’سنگل یا ریٹرن؟‘‘ تو برجو نے جلدی سے کہا، ’’سنگل۔‘‘ اور پھر پلیٹ فارم پر پہنچ کر مجھ سے بولا، ’’یہ میرا آخری سفر ہے۔ اس پر مجھے واپسی کے ٹکٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔‘‘
ٹرین روانہ ہونے سے پہلے میں نے ایک عجیب معجزہ دیکھا۔ وہ جھریوں دار چہرے اور کھچڑی بالوں والا بوڑھا اب بوڑھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے گال ایک عجیب مسرت اور جوش سے تمتما رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی زندگی چمک رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک کراراپن آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے وہ اپنا وہی پچیس برس والا برجو لگا۔
میں نے کہا، ’’برجو لکشمی بھابی کو میرا پرنام ضرور کہنا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ہم تمہارے رقیب نہیں ہیں۔‘‘
میں نے دیکھا کہ وہ نئے نویلے دولہا کی طرح شرما رہا ہے۔
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.